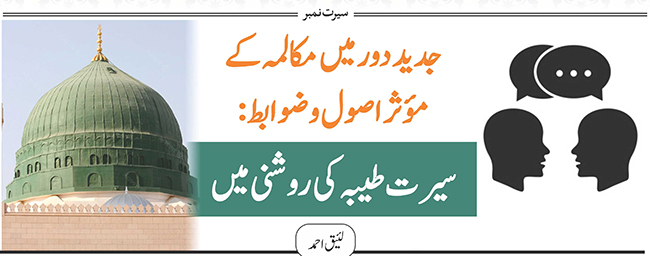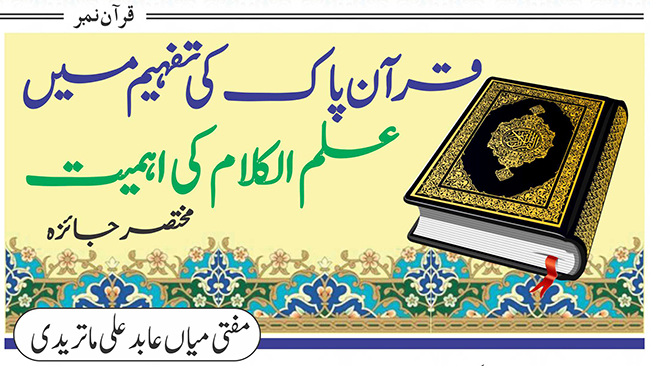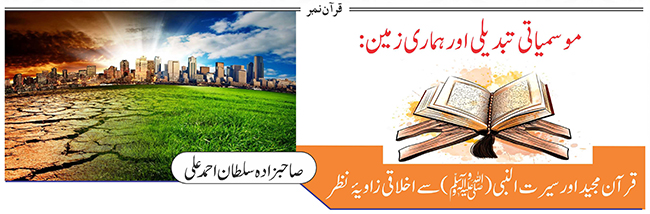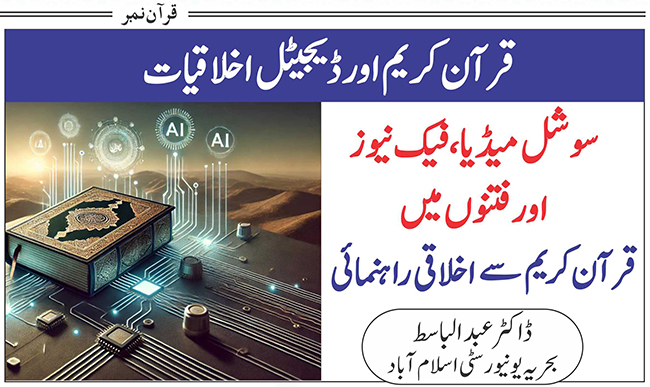جس دور میں آج ہم سانس لے رہے ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا ایک عالمی گاؤں (global village) بن گئی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کونہ صرف جانتے ہیں بلکہ بآسانی آپس میں گفت و شنید کرنے کی دسترس بھی رکھتے ہیں- البتہ جدت طرازی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب ہم اس عالمی گاؤں سے مزید سمٹ کر عالمی خیمے (global hut) کی جانب آچکے ہیں جہاں حدود و قیود سمٹ کر رہ گئی ہیں- [1]بات چیت کرنا یامؤقف پیش کرنا، اختلاف کرنایا اتفاق کرنا ، انفرادی ابلاغ و ابلاغِ عامہ، یہ سب اس جدید دور میں بے حد آسان ہوگیا ہے- البتہ انٹرنیٹ کی تیز ترین دنیا میں ایک طوفانِ بدتمیزی دیکھنے اور سننے کو آتا ہے-عدم برداشت، چند اوراق کی ورق گردانی کا غرور،حسب و نسب کا وقار، شدت پسندی اور دیگر ایسے ہی کئی عناصر اس قدر ہیں کہ کسی کا نکتہ نظر اگر سامنے والے کے اعتقاد یا نظریے کے منافی ہو تو اسے مرتبہ انسان سے ہی گرادیا جاتا ہے-سوشل میڈیا پراب کوئی بھی چیز چند سیکنڈوں میں وائرل ہوجاتی ہے اور پوری دنیا اس سے باخبر ہوتی ہے-اس اثناء میں اگر ہم مکالمہ کرنے کی اصل کو نہ سمجھیں اور اس کے اصول و ضوابط کو مدِ نظر نہ رکھیں تو بعید نہیں کہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی رہ جائے-اگر ہم عمومی طور پر بحیثیتِ انسان اور بالخصوص بطور مسلمان لوگوں کو اپنے گفتار سے فائدہ نہ پہنچا پائیں تو ہم ایک اچھے انسان نہیں کہلائے جاسکتے - کیونکہ رحمۃ اللعالمین جناب رسول اللہ(ﷺ) کا فرمان ہے:
”وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں“-[2]
ظاہر ہے کہ انسان کی زبان بھی دوسروں کو نفؑع یا نقصان پہنچاتی ہے- اس لئے کلام کرتے وقت اس کے آداب کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے-یہی وجہ ہے کہ مکالمہ کا اصطلاحی معنی اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ:
”التحدث و تعافل و قول الکلمات وتوضیح الکلام“ [3]
’’بات کرنا، باہمی انداز اپنانا کلمات کہنا یا بول کو واضح کرنا‘‘-
مکالمہ محض برتری یا اپنا مؤقف منوانے کا نام نہیں ہے- اگر مقصد فہم، علم اور قربت ہو تو مکالمہ فائدہ مند مانا جاتا ہے وگرنہ بے سود بحث و تکرار وقت کا زیاں ہوتا ہے- مکالمہ کے لیے چند اصولوں کا خیال ضروری ہے- جب بات کی جائے تو دلیل کی بنیاد پر بات کریں- ایسی دلیل پیش کریں جسے فریقِ ثانی بھی تسلیم کر سکے- مخاطب کو احترام سے سنیں- نہ تضحیک کریں نہ تمسخر- ہر شخص اپنی رائے کو عزیز رکھتا ہے- جبکہ اختلاف واضح اور شائستہ ہونا چاہئے- دوسروں کی رائے قبول یا رد کرنے کا حوصلہ رکھیں- جبرو تسلط فائدہ مند نہیں ہوتا- اسی طرح اختتام خوشگوار رکھیں- ماحول ایسا ہو کہ دوبارہ ملنے کی گنجائش باقی رہے- بہترین ہے کہ معذرت کو شعار بنائیں- اگر کوئی بات دل آزاری کا سبب بنی ہو تو اس کا ازالہ کریں- البتہ بدنیتی سے گریز کریں- دوسرے کے موقف کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کریں، گفتگو کو اپنی مرضی کا مطلب نہ پہنائیں، الغرض !اتفاق کو نمایاں کریں- اختلاف میں بھی مشترک پہلو تلاش کیے جا سکتے ہیں- یہ رویہ فاصلہ کم کرنے میں کارگر ہوسکتا ہے- حالانکہ مکالمہ ہو یا مباحثہ، لازم یہ ہے کہ موضوع پر قائم رہیں- بات کو بے سمت نہ ہونے دیں ورنہ نتیجہ سخت ہوگا- لیکن اگر بحث بے نتیجہ ہو جائے تو رک جائیں- خاموشی بعض اوقات بہترین ردعمل ہوتی ہے- ضروری ہے کہ علمی دیانت رکھیں- حقیقت کو رد نہ کریں اور تحمل سے سنیں- اگلے کی بات پوری ہونے دیں تاکہ مفہوم درست طریقے پر سمجھا جا سکے- جبکہ مخاطب کی عمر اور مرتبے کا لحاظ رکھنا بھی مکالمہ کا اصول ہے- چونکہ دینِ اسلام دینِ فطرت ہے اور رسول اللہ (ﷺ) کی حیاتِ طیبہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے- جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
’’ لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللہِ اُسْوَۃٌ حَسَنَۃٌ ‘‘[4]
’’البتہ تمہارے لیے رسول اللہ(ﷺ) میں اچھا نمونہ ہے ‘‘-
لہٰذا مکالمہ کے مؤثراصول و ضوابط بھی ہمیں سیرت ِ طیبہ سے ملتے ہیں جنہیں ہم آج لاگو کرلیں تو مکالماتی میدان میں سرخرو ہوجائیں-خواہ وہ میدان سوشل میڈیا کا ہی کیوں نہ ہو- حضور نبی کریم (ﷺ) کی حیاتِ طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ(ﷺ) اور صحابہ کرام (رضی اللہ عنھم)نے احسن انداز میں مکالمہ فرمایا- حضور نبی کریم (ﷺ) کا اندازِ مکالمہ اعلیٰ اخلاق، نرم گفتاری، وسعتِ قلب اور فہم و حکمت پر مبنی ہوتا- آپ (ﷺ) نہ سخت لہجہ اختیار کرتے، نہ طعنہ زنی، نہ آواز بلند کرتے، نہ جبر کرتے- گفتگو سنجیدہ، مدلل اور پُر مغز ہوتی- ہر فرد کی عزتِ نفس کا خیال رکھا جاتا- حتیٰ کہ شدید مخالفین کو انہی کے لہجے میں جواب نہ دیتے-آئیں، چند بنیادی اصولوں پر غور کریں-
ایک سی صفات پر غور کرنا:
قرآن مجید میں مخاطباتِ ’’یَا أَیُّهَا النَّاسُ‘‘ اور ’’یَا أَهْلَ الْکِتَابِ‘‘ مکالمے کی ہمہ گیر بنیاد فراہم کرتے ہیں- آپ (ﷺ) نے یہودو نصاریٰ، مجوسی ومشرکین اور ملحدین سب سے مکالمہ فرمایا- اہلِ کتاب کو توحید، نبوت اور آخرت جیسے اساسیات کی طرف بلایا- جبکہ دیگر اقوام سے مکالمہ مشترک انسانی قدروں کے محور پر استوار کیا- ہرقل و دیگر عیسائی حکمرانوں سے جب حضور نبی کریم(ﷺ) کا بذریعہ خطوط مکالمہ ہوا، اس میں قرآن مجید کی اس آیت کا استعمال بارہا ہوا:
’’قُلْ یٰٓاَہْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَۃٍ سَوَآءٍۢ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللہَ وَلَا نُشْرِکَ بِہٖ شَیْئًا وَّلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللہِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْہَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ‘‘[5]
’’کہہ دیجئے ، اے اہلِ کتاب! ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور سوائے اللہ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے، پس اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم تو فرمانبردار ہونے والے ہیں‘‘-
جب سامع اور مخاطب ایک دوسرے میں موجود مشترکات پر غور کریں گے تو ان کے مابین گرما گرمی میں کمی ہوگی اور امن قائم رہے گا- اس حکمتِ عملی سے ماحول سازگار اور سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا- قرآن کریم نے کلیہ بیان کیا:
’’اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَ الْمَوْعِظَۃِ الْحَسَنَۃِ وَجَادِلْہُمْ بِالَّتِیْ ہِیَ اَحْسَنُ‘‘[6]
’’آپ (ﷺ) لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف حکمت اوراچھی نصیحت سے بلائیے اوران کے ساتھ احسن طریقہ سے بحث کیجئے‘‘-
حضور پاک(ﷺ) کا اندازِ گفتگو احسن تھا- آپ فسق و فجور سے پاک کلام فرماتے تھے- تضحیک سے گریز کرتے اور عزتِ نفس پامال نہ فرماتے-یہی وجہ تھی کہ دورانِ مکالمہ لوگ آپ (ﷺ) سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے- سوشل میڈیا پر کمنٹنگ، فیڈ بیک یا کسی بھی قسم کا ردِّ عمل دینے یا آمنے سامنے مکالمہ میں جواب دینے یا ردعمل ظاہر کرنےسے قبل ہمیں ان دونوں نکات کو مدِ نظر رکھنا چاہئے کہ ہم مخاطب و سامع میں مشترک اوصاف کو جان لیں اور احسن انداز میں اپنا نکتہ بیان کریں-
تکریم و تعظیم کرنا:
جب بھی حضور رسالت مآب (ﷺ) کی بارگاہ میں کوئی وفد آتا تو آپ اس کے پہنچتے ہی مکالمہ نہ فرماتے بلکہ سازگار ماحول پیدا فرماتے- آنے والے کی مہمان داری، عزت و تکریم کا اہتمام کیا جاتا- بسا اوقات استقبال کے لئے باہر تشریف لاتے تو بعض دفعہ اس کیلئے اپنی چادر مبارک بچھاتے- [7]
زبان کی مہارت:
رسول اللہ (ﷺ) نے حضرت زید بن ثابت(رضی اللہ عنہ) کو سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تاکہ یہود سے ان کی زبان میں مکالمہ کیا جا سکے- حضرت زیدؓ نے 15 دن میں زبان سیکھ لی- آپ (رضی اللہ عنہ) حضور نبی کریم (ﷺ) کو ان کے خطوط پڑھ کر سناتے اور جوابات بھی تحریر فرماتے- [8]
یہاں ہم زبان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ مکالمہ خواہ کسی بھی طریقے سے کیا جائے، اس میں مخاطب اور سامع کو ایک دوسرے کی زبان پر مہارت حاصل ہونی چاہئے- وگرنہ مدعا سمجھ نہیں آسکتا-
خوش کلامی پر حوصلہ افزائی:
حضور نبی کریم (ﷺ)کا وفدِ ازود سے مکالمہ سیرتِ طیبہ کا نہایت لطیف، حکیمانہ اور بصیرت آموز نمونہ ہے- آپ (ﷺ) نے ان کی خوش طبعی اور شستہ گوئی کو سراہا، ان کے ایمان کے دعوے پر نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات کی اصل حقیقت بتانے کا فرمایا- اس استفسار پر انہوں نے 15 اوصاف بیان کیے- 5 ایمانی بنیادیں، 5 عملی عبادات، اور 5 وہ اخلاقی صفات جو وہ قبلِ اسلام سے نبھاتے چلے آئے تھے- حضور نبی کریم (ﷺ) نے ان کی فراست کو خراجِ تحسین پیش کیا اور ان کی روحانی و اخلاقی پختگی کو مدنظر رکھتے ہوئے مزید 5 بامعنی نصیحتیں فرمائیں- جن میں زُہد، آخرت کی فکر، جواب دِہی کا احساس اور دنیا کی بےثباتی کا شعور نمایاں تھا-
مکالمہ کا یہ اصول ہے کہ دونوں افراد ایک دوسرے کی باتوں کو تحمل سے سنیں- دعوت کا اصل جوہر جبر نہیں بلکہ فہم، تدریج، عزت اور حکمت ہے- مؤثر مکالمہ وہی ہے جو مخاطب کی سطح، خلوص اور خیر خواہی کو سمجھتے ہوئے اسے آگے کی طرف بڑھنے کی دعوت دے-
اسی طرح مکالمہ کے متعلق ایک اور سبق آموز واقعہ بیان کیا جاتا ہے- قبیلہ بنی حارث بن کعب اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا- 10 ھ میں حضرت خالد بن ولیدؓ کی دعوت پر ایمان لائے اور وفد کی صورت میں بارگاہِ رسالت (ﷺ) میں حاضر ہوئے- رسول اللہ (ﷺ) نے ان سے ان کی سابقہ فتوحات کا سبب پوچھا تو انہوں نے تین اصول بیان کیے: ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لڑائی میں پہل نہیں کرتے اور جنگ کی صورت میں متحد رہتے ہیں- حضور (ﷺ) نے ان کی تصدیق فرمائی اور فرمایا: جو جماعت ان اصولوں پر عمل کرے گی وہ ہمیشہ غالب رہے گی- [9]
حضور کا ان کی حوصلہ افزائی فرمانا اور ان کی باتوں کو سننا یہ اصول وضع کرتا ہے کہ مکالمہ میں فریقین کو چاہئے کہ وہ غیض و غضب اختیار نہ کریں، سننے کی طاقت رکھیں اور اگر کوئی بات عمدہ و بہتر لگے تو اسے سراہا جائے-
حکمت اور نفسیاتی فہم پر مبنی کلام:
رسول اللہ (ﷺ) اہل وفود کے ظاہری یا باطنی رویوں میں کوئی خامی دیکھتے تو فوری تنقید کے بجائے حکمت، نرمی اور انسانی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اصلاح فرماتے- وفدِ بلہجیم کے سربراہ ابو جری جابر بن سلیم جب بارگاہِ رسالت (ﷺ) میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تکبر کی علامت سمجھی جانے والی لمبی تہبند پہنی ہوئی تھی لیکن حضور (ﷺ) نے براہِ راست اس پر کچھ نہ فرمایا- جب انہوں نے خود نصیحت کی درخواست کی تو آپ (ﷺ) نے نہایت شفقت سے جامع ہدایات عطا فرمائیں: کسی کو گالی نہ دینا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، حتیٰ کہ پیاسے کو پانی دینا یا خندہ پیشانی سے بات کرنا بھی نیکی ہے، اور اپنا تہبند پنڈلیوں تک اونچا رکھنا کیونکہ نیچا لٹکانا تکبر کی علامت ہے جو اللہ کو ناپسند ہے-
یاد رکھیں! اصلاحی انداز اصلاحی ہی ہونا چاہئے نہ کہ تنقیدی- حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت و دانائی آج ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی میں اگر نقص یا عیب دیکھا جائے تو اسے سب کے سامنے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے- البتہ تنہائی میں سمجھانا بہتر ہے- اگر کوئی نصیحت کا کہے تب بھی سب سے پہلے اس کی اصلاح کے نام پر اس کے عیب ظاہر نہ کئے جائیں-
اسی طرح سیرتِ طیبہ میں بیش بہا اور بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے ہم مکالمہ کا حسن سیکھ سکتے ہیں-
٭٭٭
[1]Farooq, B, et al, 2025. ETIQUETTE AND REQUIREMENTS OF INTERFAITH DIALOGUE IN A MULTIDIVERSE SOCIETY: GUIDANCE FROM THE BIOGRAPHY OF THE PROPHET, Al Aasar Journal, Vol 2, No. 1.
[2]معجم الکبیرللطبرانی، ج:3، ص:203
[3]لکامل فی للغہ، المبرد، دارا حل الکوثر، کویت، ج:3، ص:770
[4](الاحزاب:21)
[5](آلِ عمران:64)
[6](النحل:125)
[7]( الطبقات الکبری از ابن سعد، ، ج:2، ص: 52)
[8]احمد بن حنبل ؒ ،ابو عبداللہ الشیبانی، الامام (م:241ھ) ’’المسند‘‘ ،حدیث زید بن ثابتؓ،ج:6، ص:238(دار احیاء التراث العربی،بیروت،1991ء)
[9] الطبقات الکبریٰ از ابن سعد، ج:1، ص:339