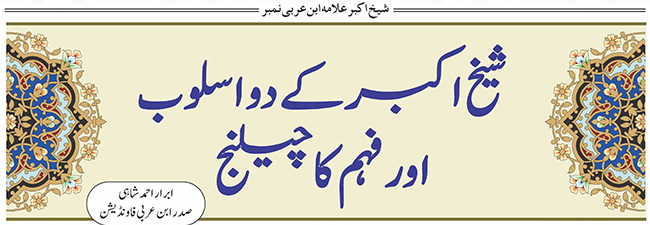آج ہم اس مختصر مقالے میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیخ اکبر محی الدین ابنِ عربی کا عمومی اسلوبِ بیان کیا ہے؟ اور یہ کہ کیا واقعی شیخ کی بات سمجھنا اِس قدر دشوار ہے جس قدر عام لوگ سمجھتے ہیں؟ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ اکثر اہلِ تصوف بھی، جو تصوف کے بنیادی مسائل کا ادراک رکھتے ہیں،اس کے باوجود شیخ کے کلام میں اصل مدعا تک نہیں پہنچ پاتے- سرسری سی بات سمجھ آ بھی جائے تو بھی وہ شیخ کی اصل گہرائی سے خود کو اجنبی ہی محسوس کرتے ہیں-
آئیے، اِنہی وجوہات کو شیخ کے اسلوب کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں -
شیخ اکبر کا عمومی اسلوب: ایک جہانِ معنی
جب ہم کتبِ شیخ اکبر کے اوراقِ قدسیہ کو کھولتے ہیں تو آپ کی تحریری روایت کو دو متمایز ادوار میں تقسیم پاتے ہیں:
پہلا اسلوب:
جب شیخ نے اپنے کشفی حقائق کو شاعرانہ اسلوب میں ڈھالا- یہ انتخاب محض اتفاق نہ تھا- حقیقت یہ ہے کہ شیخِ اکبر صوفی ہونے سے قبل ایک کمالِ فن شاعر تھے- لڑکپن ہی سے آپ اندلس کے ادبی حلقوں میں اپنی شاعرانہ شناخت قائم کر چکے تھے-عرب تقریبات میں شاعری کو جو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اس میں شیخ کی شرکت بھی ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے- اس حوالے سے ہمیں اسماعیل ابن سودکین کی کتاب ملفوظات ابن عربی میں یہ گواہی ملتی ہے-لکھتے ہیں:
’’اُس روز میں نے عثمانی سے ملاقات کی تھی ...اور وہ شاعر تھا- اس نے مجھ سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ تو (یعنی ابن عربی) مجھے مرثیہ کے معانی بتا تاکہ میں ایک شخص کے لیے ایک نظم بناؤں جس نے مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے کہ میں متنبی کے اس قصیدے کے وزن پر اس کے لیے ایک مرثیہ لکھوں:
|
أَيا خَدَّدَ اللهُ وَردَ الخُدودِ |
’’میں (ابن عربی) نے عثمانی سے کہا: تجھ سے کس نے یہ مرثیہ مانگا ہے؟ تاکہ اس کا مرتبہ جانوں اور اس کے لائق معانی بتاؤں- اس کے بعد میں نے اسے ایک شعر بتایا جو اس نظم کا پہلا شعر ہو گا اور وہ یہ ہے:
|
أيَا عَيْنُ وَيْحَكِ بِالدَّمْعِ جُودِي |
یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ شیخ تصوف میں آنے سے قبل عربی شاعری کے فنی اسرار سے مکمل آگاہ تھے ، لفظ و معنی کی باریکیوں پر حیرت انگیز عبور رکھتے تھے اور شعری اصطلاحات (وزن، قافیہ، مرثیہ) پر دسترس رکھتے تھے- لیکن اس سے بھی کہیں بڑی بات یہ تھی کہ آپ کا یہ فرمانا کہ ’’ تجھ سے کس نے یہ مرثیہ مانگا ہے؟ تاکہ اس کا مرتبہ جانوں اور اس کے لائق معانی بتاؤں‘‘-یہی وجہ ہے کہ جب آپ پر کشف و الہام کے دروازے کھلے اور جب آپ نے کتاب الاسراء جیسی رمزی کتب تحریر کیں تو اسماعیل ابن سودکین نے کہا: یا سیدی! میں تو اِس کتاب کو عالم خیال سے مقید دیکھتا ہوں؟ اس پر شیخ کا جواب ایک کلیدی وضاحت تھی - فرمایا:
’’مجھ پر یہ کشف مجرد معانی کی صورت میں ہوا، اور میرے اکثر کشف ایسے ہی ہیں- پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ قوت بخشی کہ میں معانی کو عبارت میں ڈھال سکوں اور صورتوں میں قید کروں- لہذا میں نے ان معانی کو رمزیہ عبارات میں ایسے بیان کیا ہے کہ یہ خواب کی مانند ہو گیا ہے، جس کی تعبیر وہی بتا سکتا ہے جو اس کے اصولوں سے واقف ہو‘‘-
یہی شیخ کا وہ پہلا منفرد اسلوب ہے جس میں آپ نے کشفی حقائق کے بیان کو مناسب سمجھا- یہ اسلوب ہمارے ہاں منظوم نثر یا آزاد نظم سے ملتا جلتا ہے، جہاں آپ نے مسجع اور مقفع عبارات کا استعمال کیا، خواب نما تمثیلات سے کشف کے معانی بیان کیے، استعارات سے حقائق تک رسائی کی راہ ہموار کی-
اس اسلوب کے بارے میں فرماتے ہیں:
’’مثلاً ہمارے آسمان اور زمین کہنے سے مراد یہ آسمان اور زمین نہیں، میری مراد مثلاً بلندی اور پستی ہو سکتی ہے‘‘-
اسی طرح آپ زمین سے مراد جسم اور آسمان سے مراد روح لیتے ہے- آپ سورج اور چاند کو بھی اِسی استعارے میں استعمال کرتے ہیں کہ سورج روح اور چاند نفس ہے- اپنی کتاب الاسراء میں اندلس کو دلس (یعنی تاریکی) اور بیت القدس کو قلب کی پاکی کے معنوں میں استعمال کیا-
اسی کتاب میں فرمایا: انتہائی ’’پست مقام‘‘ سے آیا ہوں، اور ’’شہر رسول‘‘ کا مسافر ہوں کہ مقام اظہر اور کبریت احمر کا متلاشی ہوں - یہاں ’’پست مقام‘‘ اسفل السافلین کا اشارہ ہے اور ’’شہر رسول‘‘ مقام محمدی کا استعارہ ہے- اسی طرح آگے چل کر تین حجابات کی بات کی: سرخ یاقوت، سرمئی یاقوت، اور زرد یاقوت ، بعد میں خود شرح کی کہ سرخ ذات کےلیے، سرمئی صفات کے لیے اور زرد یاقوت افعال کےلیے ہے- اسی طرح مجمع البحرین کی اصطلاح کہ اس کے ظاہر سے تو مراد دو سمندروں کا ملنا ہے لیکن شیخ نے اس سے روح اور جسم کا اتصال مراد لیا- یہ اور اس طرز کی دیگر لا تعداد مثالیں اس بات کی گواہ ہیں کہ شیخ نے اپنے ابتدائی دور میں کشفی حقائق کے بیان کے لیے شاعرانہ اسلوب کا استعمال کیا ہے -
آپ کا یہ طرز تحریر زیادہ تر آپ کے ابتدائی دور کی کتب میں نمایاں ہے، جیسے کتاب الاسراء، عنقاء مغرب، مواقع النجوم کا ایک حصہ، مشاہد الاسرار القدسیہ وغیرہ- اسی طرح شہر مکہ میں لکھا گیا رسالہ تاج الرسائل ومنہاج الوسائل اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی چند کتب بھی اسی اسلوب کی حامل ہیں: ان میں تنزلات الموصلیہ اور فتوحات مکیہ کے چند حصے شامل ہیں-
دوسرا اسلوب:
اسی طرح سن 595 ھ کے بعد لکھی گئی اکثر کتب میں شیخ نے ایک دوسرا اسلوب اپنایا- اس اسلوب میں آپ نے ان کشفی حقائق کی تعبیر کے لیے اصطلاح سازی پر توجہ دی، اس سے قبل آپ انہیں رمز و استعارے کی زبان میں لکھتے آ رہے تھے لیکن اب آپ نے انہیں عقلی پیمانوں پر قلم بند کرنا شروع کیا- اسی حوالے سے آپ اپنی کتاب انشاء الدوائر کے مقدمے میں لکھتے ہیں:
’’جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اشیا کے اصلی حقائق، ان کی باہمی نسبتوں اور اضافتوں سے روشناس کروایا، تو میں نے اپنے ساتھی عبداللہ بدر الحبشی کی سہولت کے لیے ان مجرد حقائق کو حِسّی شکلوں اور خاکوں میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا تاکہ میرے ساتھی اور دوست عبد اللہ بدر الحبشی پر اِن کا سمجھنا آسان ہواور یہ سب ہر اس شخص پر بھی واضح ہو سکے جو کشف سے ان تک نہیں پہنچا، یا پھر اس کی محدود فکر ان کے ادراک سے عاجز ہے‘‘-
اس جدید اسلوب سے شیخ اکبر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ضعیف البصیرت افراد کے لیے تجریدی حقائق کو فہمِ انسانی کے قریب لایا جائے اور ثانیاً، سطحی فکر رکھنے والوں کو وجود میں ان کے حقیقی مقامِ کا ادراک دِلایا جائے- اِس مقصد کے تحت آپ نے خاکوں، دائروں اور محسوس مثالوں کے ذریعے معقول مفاہیم کو مجسم شکل دی اور یوں اپنے بیانیے میں ایک انقلابی اسلوب اپنایا- یہ انداز اُن کے شاعرانہ رمزیہ اسلوب سے یکسر مختلف تھا، جہاں استعارات و رموز کی کثرت کے برعکس اصطلاحات کی منضبط تشریح کو مرکزی حیثیت دی گئی- ہر نئی اصطلاح (اعیانِ ثابتہ، انسانِ کامل،حاضرات الہیہ) کی تعریفی حدود واضح کی گئیں اور فلسفیانہ حقائق کو منطقی تسلسل سے پیش کیا گیا-
شیخ کے اِس اسلوب میں وضع کی گئی یہ نئی اصطلاحات اس قدر کثیر تھیں کہ معاصر محققہ سعاد الحکیم کو ان کے شمار کے لیے ایک کتاب ’’مُوَلِّدُ لُغَةٍ جَدِيدَةٍ‘‘ لکھنی پڑی اور بعد میں ’’المعجم الصوفی‘‘ نامی کتاب میں آپ نے اِن کی تفصیلی تشریح بھی پیش کی- یہ کام اِس حقیقت کا غماز ہے کہ ابنِ عربی نے نہ صرف تصوف کو نئی اصطلاحات دیں بلکہ عربی علمی زبان کی وسعت میں اپنا کردار ادا کیا -
شیخ کا یہ اصطلاحاتی اسلوب محض ’’اندازِ بیان‘‘ نہ تھا، بلکہ تصوف کی علمی بنیادوں کو مزید قوی و توانا کرنے کی کاوش تھی-جہاں پہلے دور میں آپ نے رمز و خیال کی زبان اختیار کی، وہیں اب اصطلاحات کی لغت، تشریحی خاکے اور منطقی تعریفوں کے ذریعے علوم تصوف کو ایک دستاویزی نظام میں ڈھالا، جو آج تک عالمِ تصوف کی علمی تشکیل میں حرفِ آخر ہے-
اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیخ کے ان دو اسلوبوں کا سمجھنا عام قاری پر دشوار کیوں ہے؟ ہمارے طویل مطالعہ و ترجمہ کے تجربے کے مطابق اس کی وجوہات پانچ اہم نکات میں سمٹتی ہیں:
1- ظاہر پرستی کا حجاب
اس کی پہلی وجہ تو شیخ نے خود بیان کر دی، کہتے ہیں:
’’جب میں ’آسمان و زمین‘ کہتا ہوں تو مراد یہ مادی آسمان و زمین نہیں، بلکہ بلندی و پستی کے معانی ہیں‘‘-
مگر مسئلہ یہ ہے کہ عام مذہبی قاری کی تربیت ہی ظاہری الفاظ کے حصار میں ہوتی ہے- اِسے لغوی معنی کو حتمی سمجھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے- جب وہ شیخ کے استعاروں کو حرفی معنوں میں لیتا ہے تو ظاہری الفاظ میں اٹک جاتا ہے-باطنی معنی تک رسائی ممکن نہیں رہتی، نتیجتاً اسے مایوسی اور بددلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے-
2-استعاروں کی کثرت:
اس کی دوسری وجہ استعاروں کی کثرت ہے- اگر تحریر میں دو چار استعارے ہوں تو پھر بھی گنجائش رہتی ہے کہ قاری انہیں سمجھ لے گا مگر جس کا اسلوب ہی ایسا ہو کہ ہر جملہ رمز و استعارے سے پر ہو- ہر لفظ کئی تہوں میں لپٹا ہو (جیسے: سورج = روح، چاند = نفس، یاقوتِ سرخ = انوارِذاتِ الٰہی) تو پھر مدعا تک رسائی آسان نہیں رہتی- جب پوری عبارت ہی استعاروں کا جنگل بن جائے تو قاری بے چارہ بھی کیا کرے - یوں وہ کسی ایک کلید سے یہ تالا نہیں کھول پاتا اور اصل معنی اور مدعا سے بھٹک جاتا ہے-
3- کشفی تجربے کا نہ ہونا:
چونکہ آپ کی تحریریں اکثر براہِ راست کشفی مشاہدات اور الہامی واردات کا نتیجہ ہیں اور یہ زبان منطقی استدلال کی ترتیب سے بالاتر ہو کر ایک خاص ’’حال‘‘ یا ’’مقام‘‘ کی پیداوار ہے- جو قاری خود اُس ’’حال‘‘ سے روشناس نہیں، اُس کے لیے اس زبان کو محض عقلی ترازو میں تولنا ممکن نہیں رہتا- جیسے بھوکے کے لیے کھانے کے ذائقے اور خوشبو کا بیان بے معنی ہے ویسے ہی باطنی احوال سے ناآشنا قاری کے لیے کشف کی زبان ناقابل ادراک ہے- اس لئے کتبِ صوفیاء پڑھنے سے قبل صحبتِ صوفیاء کا حصول ضروری ہے-
4- حقائق اور اصطلاحات سے ناواقفیت:
اس کی چوتھی وجہ حقائق اور شیخ کی اصطلاحات سے ناشناسی بھی ہے- شیخ نے اپنے مخصوص تصورات کو واضح کرنے کے لیے ایک نفیس نظامِ اصطلاحات وضع کیا، مثلاً حق، خلق، برزخ، عالمِ مثال، انسانِ کامل، اعیانِ ثابتہ وغیرہ- اگر قاری شیخ کے اس اصطلاحی نظام سے واقف نہیں، تو پھر وہ بے کلید قفل کھولنے کی کوشش کرنے والے اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والے شخص کی طرح بے سود رہ جاتا ہے-
5-مفاہیم کی ہمہ گیری اور وسعت:
ابنِ عربی کا علمی دائرہ حیرت انگیز طور پر وسیع ہے- قرآن و حدیث، فقہ و کلام، فلسفہ و منطق، فلکیات و عددیات، اور مختلف مذاہب کے علوم، یہ سب آپ کے ہاں یکجا ہو جاتے ہیں- ایک ہی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے آپ ان تمام شعبوں کے حوالے اور تناظر میں بات کر تے ہیں، جو ناواقف قاری کے لیے الجھن کا باعث بنتا ہے-
ایک عام قاری اس سلسلے میں کیا کرے؟:
شیخ اکبر کی تحریروں کی دشواریاں اپنی جگہ مسلّم ہیں، مگر ہر گز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ علوم ناقابل فہم ہیں- اگر ایسا ہوتا تو پھر شیخؒ کا یہ عظیم علمی ذخیرہ محض عبث اور رائیگاں ہوتا- تحقیق اور مشاہدے کے مطابق ایک عام قاری مندرجہ ذیل علمی اقدامات اٹھائے تو ممکن ہے کہ وہ بھی خواص کے اس گروہ میں شامل ہو جائے جن کے لیے یہ علوم وضع کیے گئے-
1- مذہبی علوم سے روشناسی
سب سے پہلے اسے علوم اسلامیہ کے مطالعے کی عادت ڈالنی ہو گی- قرآن و حدیث کی معرفت حاصل کرنی ہو گی، تفسیر کے اصولوں اور مناہج سے واقفیت حاصل کرے، احادیث کی زبان دانی، روایت و درایت اور علوم حدیث کی پہچان کے قابل ہو- فقہی مکاتب فکر کا تقابلی مطالعہ کرے، خود کو اسی ایک فرقے یا مکتب فکر کی قید میں محصور نہ رکھے کہ شیخ کو پڑھنے کے بعد بھی اس نے اسی جانب جانا ہے- اسی طرح تصوف کے بنیادی نظریات جیسے، تزکیہ نفس، مقامات و احوال، شریعت و طریقت، سلوک و سفر کی خبر رکھنا بھی ضروری ہے- اس کا اتنا مطالعہ ہونا چاہیے کہ ان علوم کی بنیادی اصطلاحات کو نہ صرف سمجھتا ہو بلکہ اتنا جانتا ہو کہ اگر ان کی جانب اشارہ بھی کیا جائے تو فورًا جان لے- یوں اسے ایک ایسی بنیاد مل جائے گی جو بعد میں اسے شیخ اکبر کے بیان کردہ علوم میں معاون ہو گی-
2- شیخ کی آسان کتب سے شروعات کرے:
جب اس کی علمی بنیاد مستحکم ہو جائے تو اب شیخ کی قدرے آسان کتب سے مطالعے کی ابتدا کرے، وہ کتب جو نہ استعارات اور اشارات سے بھرپور ہوں اور نہ ہی دقیق اصطلاحات کے بوجھ تلے دبی ہوں- مثلاً وہ علم حدیث میں شیخ کی لکھی گئی کتب’’101 احادیث قدسی‘‘ یا ’’المحجہ البیضاء‘‘ کا مطالعہ کر سکتا ہے- اصلاح نفس اور بزرگوں کے احوال کی معرفت کے لیے ’’روح القدس فی مناصحہ النفس‘‘ اور ’’مختصر الدرة الفاخرہ‘‘ کو پڑھ سکتا ہے- عالم اکبر اور عالم اصغر کی مناسبت اور اس مملکت انسانی کی اصلاح میں خدائی تدبیرات کے لئے ’’التدبیرات الالہیہ‘‘ پڑھ سکتا ہے- ’’مواقع النجوم‘‘ کے اکثر حصے آسان زبان میں تحریر کردہ ہیں جو اس کے لیے معاون ہوں گے- خاص کر فتوحات مکیہ کا آخری باب لازمی پڑھے-یہ سب کتب اسے شیخ کے اسلوب سے متعارف کروائیں گی، اسے شیخ کی اصطلاحات اور انداز کا پتا لگنا شروع ہو جائے گا- جب آہستہ آہستہ وہ یہ سب پڑھ لے گا تو پھر باقی کتب کی جانب جانا آسان ہو جائے گا-
3- اصطلاحات شیخ سے آشنائی:
جب قاری مندرجہ بالا آسان کتب کے ذریعے شیخِ اکبر کے علوم تک رسائی پاتا ہے تو سب سے بڑا امتحان اصطلاحات کا ہوتا ہے- یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ عام مذہبی لٹریچر میں استعمال ہونے والے الفاظ (عشق، قلب، روح، برزخ) کے روایتی معنی ذہن میں رچ بس گئے ہوتے ہیں-قاری بے ساختہ اِنہی معانی کو شیخ کی اصطلاحات پر ٹھونس دیتا ہے-حالانکہ شیخ نے اِنہی الفاظ سے اپنے علوم میں اپنے خاص معانی مراد لیے ہوتے ہیں-
اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہ تین عملی اقدام اٹھائیں:
- سب سے پہلے آپ اس اصطلاح میں مصنف کی تعریف ڈھونڈیں کیونکہ شیخ نے ہر اہم اصطلاح کی وضاحت اپنی کتب میں جا بجا کر رکھی ہے- ہو سکتا ہے کہ مترجم نے حاشیے یا فٹ نوٹ میں یہ تعریف فراہم کی ہو- ایسی صورت میں اسے رٹ لیں کہ جب بھی یہ اصطلاح آئے آپ اس کی تعریف جانتے ہوں-
- آپ اپنی ذاتی اصطلاحاتی لغت بنائیں- ایک ڈائری یا رجسٹر میں شیخ کی اصطلاحات اور ان کی تعریفات لکھتے جائیں- یوں نہ صرف آپ انہیں سمجھ لیں گے بلکہ ضرورت پڑنے پر اس کی جانب رجوع بھی کر سکیں گے-
- سیاق و سباق پر خصوصی توجہ دیں - عمومی مشاہدے میں آیا ہے کہ شیخ نے ایک اصطلاح کے دسیوں معنی بھی بنا رکھے ہیں- اگر آپ قرینہ کلام کو نہ سمجھ پائے اور اس پر غلط معنی کا اطلاق کر دیا تو بھی غلطی کھائیں گے-
اس کی بہترین مثال لفظ ’’عین‘‘ ہے جو آپ کے ہاں متعدد معانی رکھتا ہے جن میں: وجود، حقیقت، آنکھ، سرچشمہ، ذات، عدمی وجود، عین ثابت اور دیگر بہت سے معانی ہیں- اگر قاری صحیح سیاق و سباق میں درست معنی کا اطلاق نہیں کرے گا تو لازماً غلطی کھائے گا- شیخِ اکبر کی اصطلاحات مردہ لغوی الفاظ نہیں، بلکہ زندہ وجودی حقائق ہیں- جب آپ ’’عین‘‘ کو لغت میں ڈھونڈتے ہیں تو اس کا مطلب آنکھ ملتا ہے، مگر جب اسے شیخ کے سیاق میں پڑھتے ہیں تو یہ وجود اور حقیقت نظر آتی ہے- اِس فرق کو پا لینا ہی حقیقی عرفان کی پہلی سیڑھی ہے-
4- کسی استاد سے رابطہ کریں:
شیخِ اکبر کے علوم کی فہم میں خواہ آپ کتنی ہی ترقی کر لیں، ہر لمحہ یہ احساس دامن گیر رہتا ہے کہ یہ بحرِ بیکراں کوئی حوضِ خانہ نہیں جس کی تہہ تک پہنچا جا سکے- یہی وجہ ہے کہ ابتدا ہی سے اِن متون کی شروحات لکھنے کی روایت چلی آ رہی ہے،محض فصوص الحکم پر 150 سے زائد شروحات اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں- مگر المیہ یہ ہے کہ بیشتر شروحات عربی میں ہیں، جبکہ اردو،فارسی،ترکی دان طبقہ ان سے محروم رہ جاتا ہے- اس پر طرفہ یہ کہ بعض شارحین نے نظام اصطلاحات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے کہ قاری بات سمجھنے کی بجائے اصطلاحات کے گورکھ دھندے میں بھٹک جاتا ہے اور متن سے براہِ راست رشتہ ٹوٹ جاتا ہے-
ایسی صورت میں واحد حل استاد ہی ہے- شیخِ اکبر خود فرماتے ہیں: ’’میرا یہ علمِ خواب کی مانند ہے جسے کوئی مُعَبِّر(یعنی تعبیر جاننے والا ماہر ) ہی سمجھ سکتا ہے‘‘-
اسی اصول پر ایسا استاد ہونا چاہیے جونہ صرف شیخ کے ان علوم کی ظاہری جہت سے واقف ہو، بلکہ عملی سلوک کے ذریعے اِن حقائق کو زندگی میں ڈھال چکا ہو- جو لفظوں کو مردہ مفاہیم نہ سکھائے، بلکہ وجودی حقائق کی چاشنی تک پہنچائے -
5- عملی تصوف میں شریک ہوں:
شیخِ اکبر کے علوم کوئی مجرّد فلسفہ نہیں جسے سمجھ لینا کافی ہے- یہ تو راہِ سلوک ہے جس پر چل کر حق تک پہنچا جاتا ہے، یہ عملی ضابطۂ حیات ہے جس میں روح و جسم سے اُترا جاتا ہے، اِسے دل میں بٹھایا جاتا ہے اور اپنے ظاہر و باطن کو اِس پر لایا جاتا ہے- اپنی کتاب تدبیرات الہیہ کے خاتمے میں شیخ یہی فرماتے ہیں:
’’اے مرید اپنے نفس کی نجات کو جان، سب سے پہلے اپنے لیے کوئی ایسا استاد ڈھونڈ جو تجھے تیرے نفس کے عیوب دکھائے، جو تجھے تیرے نفس کی غلامی سے نجات دلائے، اگرچہ اُس کے لیے تجھے دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے‘‘-
٭٭٭