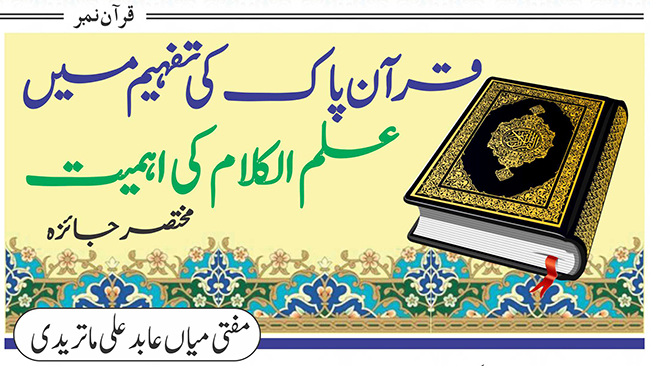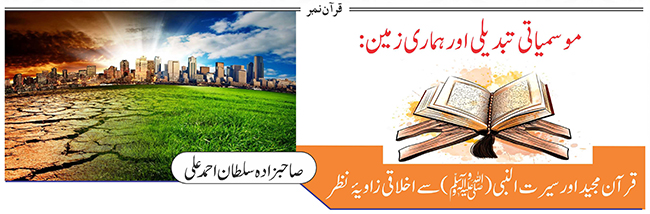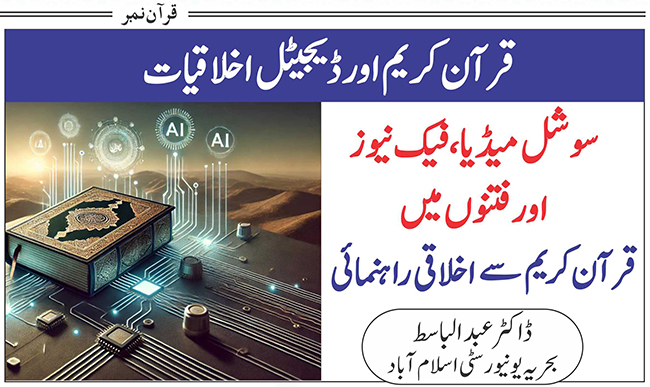علامہ محمد اقبالؒ کی یہ ’’Allegory of the Grave‘‘ یعنی تمثیلِ مزار اتفاقیہ طور پہ افلاطون کی ’’Allegory of the Cave‘‘ یعنی تمثیلِ غار سے کچھ بین المتنی (Intertextual) تعلق ظاہر کرتی ہے - افلاطون کی غار والی مثال میں لوگ ایک غار میں قید ہیں اور سایوں کو حقائق سمجھتے ہیں اور اُن کیلئے یہی کافی ہے- اس قید سے آزاد ہوجانے والا شخص ہی جانتا ہے کہ سایوں کو حقائق سمجھنا اور اسی پہ اکتفا نیز وسیع کائنات کو چھوڑ کر ایک غار کی قید کس قدر اذیت ناک عمل ہے - اقبال کی اس نظم ’’عالَمِ برزخ‘‘ میں بھی مُردہ موت کو آخری و اَبدی حقیقت سمجھتا ہے اور اس کیلئے ظلمت کدۂ خاک میں رہنا ہی آسودگی ہے، جبکہ قبر اس حقیقت کو جانتی ہے کہ موت کا لازمی تقاضا تو ’’مر کے جی اٹھنا‘‘ہے مگر یہ کام صرف آزاد لوگوں کا ہے- آزاد کے نزدیک قیامت کے اٹھائے جانے کا مرحلہ حیاتِ نو ہے-مگر اس غلام مردے کے نزدیک اذیت ہے - غار کی طرح حقائق قبر سے باہر موجود ہیں قبر کے اندر نہیں - [1]
’’عالمِ برزخ‘‘ ایک تخیلاتی مکالمے پہ مبنی نظم ہے ، برزخ یعنی اس جہان اور قیامِ قیامت کے مابین کی دنیا، جو کہ قبر کا عرصہ ہے - وہاں مردہ اپنی قبر سے ایک سوال کرتا ہے، قبر اُس سوال پہ تعجب بھی کرتی ہے اور جواب بھی دیتی ہے- جواب سُن کے مردہ اپنا تبصرہ کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے - اس سے آگے ایک منظر ہے جو نظم میں لکھا تو نہیں ہوا مگر مفہوم میں موجود ہے کہ قبر نے مردے سے جو کچھ سُنا اس پہ قبر کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، جس پہ غیب سے کوئی آواز قبر کو اُس مردے کے تبصرے کا مطلب سمجھاتی ہے - غیب کی آواز سے قبر پہ عُقدہ کشائی ہوتی ہے اور وہ مردے پہ اپنا تبصرہ کرتی ہے اور حضرت اسرافیل کو، ذاتِ حق کو اور جانِ پاک یعنی حضرت جبرائیل کو ندا دیتی ہے - پھر غیب سے ایک صدا برآمد ہوتی ہے جس کی سماعت کے بعد زمین اختتامی خطاب کرتی ہے اور نظم اختتام پذیر ہو جاتی ہے -
نظم کا مرکزی مضمون ’’آزادی اور غلامی‘‘ہے، اس میں استعمال ہونے والی علامتیں، تشبیہیں اور استعارے اِسی پسِ منظر میں بُنے گئے ہیں - اُن میں سے چند ایک یہ ہیں:
مردۂ صد سالہ ہندی مسلمان ہے، قبر وہ مٹی وہ خاک اور وطن ہے جس میں یہ رہتا ہے - موت فرنگ کی تہذیبی و فکری غلامی کو قبول کرنا ہے- ظلمت کدۂ خاک سے بیزار نہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ اس غلامی پہ رضا مند ہو چکا ہے- قیامت اس غلامی کے خول سے آزادی حاصل کرنا اور ایک حریت پسندانہ آزادانہ انقلاب ہے جو غلامی کے جال پھینکے جانے کے بعد ہر آزاد شخص پہ لازم ہے- روح سے مراد اسلامی تہذیب و تمدن ہے - بدن سےمراد بدن بذاتِ خود بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی ہے- صدائے غیب صدائے حق ہے جس کا مہبط اقبال کا ضمیر ہے - مرگِ ابد یعنی ہمیشہ کی غلامی- بانگِ سرافیل کو ان معنوں میں برتا گیا ہے کہ یہ قدرت کے وہ آوازے ہیں جو مختلف حادثات و واقعات کی صورت میں ضمیر کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں -
عالمِ بَرزخ
(مُردہ اپنی قبر سے)
|
کیا شے ہے، کس امروز کا فردا ہے قیامت؟ |
قیامت کیا ہے؟ (وہ) کس آج کی ہونے والی کل ہے؟ اے میری مستقل قیام گاہ! (اے میری قبر) قیامت کیا ہے؟
آئندہ سطور میں یہ بات بزبانِ شاعر بھی آ جائے گی اور اسے تمہید میں بھی ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ یہ مردہ ایسے لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اغیار کی غلامی کو قبول کر لیا ہوتا ہے - اسے سو سال بعد معاً خیال آتا ہے کہ قیامت کا نام تو بہت سُنا مگر قیامت کا معلوم نہیں کہ قیامت کیا ہوتی ہے، کیوں نہ اپنی قبر سے یہ پوچھا جائے؟
قبر
|
اے مُردۂ صد سالہ! تجھے کیا نہیں معلوم؟ |
اے سو بر س سے (مجھ میں دفن) مُردے! کیا تجھے (اتنا بھی) نہیں معلوم کہ ہر موت کے بعد ’’قیامت‘‘ یعنی قیام/ اٹھایا جانا لازمی امر ہے -
یہاں مردے کے دفن ہونے سے یہ مکالمہ کرنے تک کا دورانیہ سو سال بیان ہوا اور نظم میں آگے بھی سو سال پہ اصرار کیا گیا ہے ، اسے محض اتفاق کہہ کر بھی بات ٹالی جا سکتی ہے لیکن اس میں کچھ پوشیدہ بھی تو ہو سکتا ہے - ارمغانِ حجاز اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی اور اس کی نظمیں غالباً 1935ء – 1936ء کے زمانے کی ہیں ، اِس تناظر میں ایک سو سال کا تعین واضح اشارہ بنتا ہے انگریز کے پہلے تعلیمی قانون کی طرف جو کہ 1835 ء میں آیا - اس کے محض بائیس برس بعد یعنی 1857 ء میں باضابطہ انگریزی قبضہ ہوا - گو کہ ہندوستان اور خاص کر اسلامیانِ ہند، فرنگی غلامی تو بہت پہلے قبول کر چکے تھے - کلکتہ فورٹ ولیئم کا قیام، جنگِ پلاسی، جنگِ بکسر، سقوطِ سرنگا پٹم، اینگلو مرہٹہ جنگیں، آسام و برما پہ قبضہ اور تابوت میں آخری کیل1835 ء کی تعلیمی اصلاحات - گویا یہ مردۂ صد سالہ واضح اشارہ ہندی مسلمان کی طرف تھا -
پہلے مصرعے میں نہایت درجے کا تعجب ہے، سوالیہ حیرت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ موت کے بعد قیامت جیسی بنیادی سی بات سے بھی یہ مردہ بے خبر ہے؟ گوکہ اس نظم کے مضمون میں یہ براہِ راست تو شامل نہیں لیکن شاعر کے ذہنِ رسا کے کسی گوشے میں یہ فکر موجود ہے کہ غلامی کی علامات میں ایک علامت جہالت اور حقائقِ عالم سے بے خبری بھی ہے ، تبھی تو وہ مردہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ جیسی بنیادی بات سے بھی بے خبر ہے -
اسلامی عقائد میں ’’معاد‘‘ کا عقیدہ اور اس کی جزئیات نہایت اہمیت رکھتی ہیں- اُن میں ’’بعث بعد الموت‘‘ یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا لازمی اور قطعی ہے - قبر اپنے مُردے کو یہ بنیادی عقیدہ یاد دلاتی ہے کہ تمہیں اس قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور دوبارہ اٹھائے جانے کا دن قیامت کا دن کہلاتا ہے ، جیسا کہ لفظِ قیامت سے بنفسہٖ یہ واضح ہے کہ یہ قیام یعنی کھڑا ہونے یا کھڑا کئے جانے کے معنی میں ہے -
اگر اقبال کی اردو/فارسی کلیات میں جھانکا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے مستقل دلچسپی و فکر کے موضوعات میں قیامت کا موضوع بھی شامل تھا- قیامت اور اس کے مترادفات کو جتنے تنوّع سے اردو و فارسی شاعری میں اقبال نے برتا ہے ، شاید ہی مولانا رومیؔ اور میرزا بیدلؔ کے علاوہ کسی شاعر نے ایسے برتا ہو- اس دعوے کی تائید میں دونوں کلیات موجود ہیں، اگر انتخاب کے طور پہ پیش کیا جائے تو بالِ جبریل میں اقبال مُریدِ ہندی کے روپ میں اپنے پیرِ رُومی سے پوچھتے ہیں :
|
سرِّ دیں اِدراک میں آتا نہیں |
پیرِ رُومی جواب مرحمت فرماتے ہیں :
|
پس قیامت شو، قیامت را ببیں |
’’پس (تو خود) قیامت بن جا، (تب ہی) قیامت کو دیکھ (پائے گا)، ہر شے کو دیکھنے کیلئے ایک یہی شرط ہے‘‘-
زیرِ مطالعہ بنیادی شعر کا دوسرا مصرعہ ’’ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت‘‘اس کو ماقبل آخری بند سے کمال مناسبت ہے جہاں صدائے غیب سے اقبال نے قیامت کے مرتب ہونے کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’زلزلوں سے وادیوں میں تازہ چشموں کی نمود‘‘- موت سُلاتی ہے جبکہ قیامت جگائے گی ، یوں موت عملِ تخریب اور قیامت اس کے نتیجے کے طور پہ نئی تعمیر - زلزلہ بھی موت کی طرح ایک تخریب ہے لیکن زلزلے کے نتیجے میں تازہ چشمے کا جاری ہونا ایک نئی تعمیر ، یوں اس تطبیق نے نظم کا آغاز و اختتام مربوط کر دیا ہے اور یہ باکمال شاعرانہ خُوبی ہے -
مُردہ
|
جس موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت |
(اے میری خاکِ لَحَد!) جس مرنے کا ایک چھپا ہوا تقاضا دوبارہ اٹھنا بھی ہے - میں ایسی موت کے پھندے میں پھنسا ہوا نہیں ہوں -
یہاں اس مردے کا تصورِ مرگ واضح ہوجاتا ہے کہ اُس نے ایسی موت کو قبول نہیں کیا جو دوبارہ زندہ ہونے دے گی جیسا کہ آزاد شخص کا تصورِ موت کہ (ہے یہ شامِ زندگی صُبحِ دوامِ زندگی) بلکہ اگر بین السطور غور کیا جائے تو دوسرے مصرعے سے یہ بہت اچھی طرح واضح ہو رہا ہے کہ وہ تعمیرِ نو یا بعثِ نو دینے والی موت کو دامِ فریب سمجھتا ہے جبکہ ابدی موت یعنی ایسی موت جس کے بعد زندگی کا کوئی تصور ہی نہ ہو؛ اسے دوبارہ اٹھنے تک سُلانے والی موت پہ ترجیح دیتا ہے - غلامی ’’حیات بعد الموت‘‘ کی صلاحیت چھین لیتی ہے-
ایک اور بات جو اس نظم میں براہِ راست تو کہیں نہیں ہے لیکن اقبال ؒ کی طرح اگر حِسِّ ظرافت سے کچھ کام لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے سے انکاری مردے میں کچھ اثر تو غلامی کا تھا اور کچھ جراثیم الحاد کے بھی پائے جاتے تھے- کیونکہ ملحدین مرنے کے بعد حشرِ اجساد کے قائل نہیں- ویسے مجموعی اقبالیاتی تناظر (Iqbalian Paradigm) میں الحاد بھی غلامی ہی کی دَین ہے- 1835ء کا تعلیمی ایکٹ ذہن میں رکھ کر بانگِ درا کا یہ شعر پڑھئے تو شک نہیں رہے گا کہ یہ مردہ ملحد غلام تھا:
|
ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم ٭٭٭٭٭ ہر چند کہ ہوں مُردۂ صد سالہ و لیکن |
یہ ٹھیک ہے کہ مجھے مرے ہوئے ایک سو برس ہو گئے ہیں - مگر تہہ بہ تہہ خاک کی سیاہ تاریکیوں سے میں بیزار نہیں ہوں -
مردے کی بات میں یہ خیال موجود ہے کہ زمین جواباً کہہ سکتی ہے کہ تجھے مرے ہوئے اور اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں دفن ہوئے ایک صدی بیت چلی کیا تو اس موت، تاریکی اور پڑے رہنے سے اُکتایا نہیں؟ اس لئے مُردہ اس کے جواب سے قبل ہی اپنا ’’ریشنیل‘‘ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہاں یہ درست ہے سو برس کا قدیم مردہ ہوں مگر اندھیرے سے اُکتایا نہیں ہوں - مُردہ غلامی کی موت، بیکارگی اور اندھیروں سے اس قدر مانوس ہو چکا ہے کہ آزادی اور عمل کی زندگی اور روشنی اسے بارِ ناقبول لگتی ہیں -مادیّت پرستانہ فکر و فلسفہ کی سیاہ پٹی اس کی آنکھوں پہ یوں جکڑی ہے کہ وہ اس تاریکی و سیاہی کو نُورِ بصیرت کے اجالے پہ ترجیح دیتا ہے -
اگر غور کیا جائے تو ’’ظلمت کدۂ خاک‘‘ کی ترکیب کے پیچھے کچھ اور بھی ہے ، ملاحظہ فرمایئے - اللہ پہ ایمان نُور ہے اور اس کے ہونے پہ شک کرنا ظلمت و تاریکی ہے – ’’کدہ‘‘ کا معنی مقام ، ٹھکانہ یا مسکن ہے، اس تناظر میں ظلمت کدہ سے مراد وہ تعلیمی ادارے اور نظام بھی ہیں جو ایمان و یقین کے مقابلے میں ’’ظن و تشکیک‘‘ کو فروغ دیتے ہیں- خاک مٹی ہے اور اشارہ مادہ (Matter) کی طرف ہے- مُردہ کہتا ہے کہ ’’ظلمت کدۂ خاک سے بیزار نہیں میں‘‘، گویا نورِ ایمان کے مقابلے میں ظن و تخمین و تشکیک اور مادہ پرستی کو مغرب کی چکا چوند تہذیب سے مرعوب و مغلوب ہو کر قبول کر بیٹھا ہے- اگلے شعر میں بھی روح و بدن کی اصطلاح نور و ظلمت یعنی ایمان و تشکیک کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے کیونکہ بدن کثیف و تاریک ہے اور روح لطیف و منور ہے -
|
ہو رُوح پھر اک بار سوارِ بدنِ زار |
رُوح ایک مرتبہ پھر میرے بدن پہ سوار ہو جائے گی؟ اگر اِسی کا نام قیامت یا دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا ہے تو مجھے اس کا کوئی شوق نہیں -
اس کے پہلے مصرعہ میں اشارہ ہے کہ یہ شخص اک بار ملنے والی زندگی میں بھی روح سے بیزار اور بدن کا پجاری تھا اور یہ حالت اس قدر شدید تھی کہ اسے موت کے بعد بھی بدن پرستی کی خاطر روح سے بیزاری یاد رہی- اب قیامت سے خائف ہونے کی وجوہات میں اس کےلئے یہ اہم ہے کہ بدن کو روح سے بیگانہ رکھے-اقبال کے فلسفہ میں جا بجا روح کی بیداری پہ زور دیا گیا ہے یہ اسی مضمون کے تسلسل میں ایک نظم ہے جس میں روح سے بیزار شخص کو غلامی کی بد ترین قِسَم میں مبتلا قرار دیا گیا ہے - درجنوں مثالیں کلامِ اقبال سے دی جا سکتی ہیں:
|
تنِ بے رُوح سے بیزار ہے حق |
|
اِسی مضمون میں کیسا زندہ مصرعہ ہے کہ ( دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامانِ موت)- ’’محراب گُل افغان کے افکار‘‘ والی نظموں میں بھی زیادہ تر بند حریت و آزادی کے موضوع پہ ہیں، اُس کے پہلے ہی بند میں حریت اور حفظِ روح کو باہم دگر متصل رکھا گیا ہے - اقبال فرماتے ہیں:باز نہ ہوگا کبھی بندۂ کُبک و ہمام |
حریت پسند انسان کہتا ہے کہ شاہین کبھی بھی کبوتروں فاختاؤں کی غلامی قبول نہیں کرے گا، کبوتر اور فاختہ کے نزدیک بدن کی حفاظت مقصدِ حیات ہے جبکہ شاہین کا مقصدِ حیات حفظِ رُوح ہے- لہٰذا ہر آزاد شخص کے نزدیک آزادی روح کی آزادی ہے اور غلامی روح کی غلامی ہے - فرنگی تہذیب کی ہیبت تلے دبے ہوئے غلاموں کو ایسی کوئی حرکتِ فکر و عمل نہیں چاہئے جس سے روح یعنی اسلامی تہذیب و تمدن پھر سے سوارِ بدنِ زار ہو یعنی اجتماعی زندگی کا حصہ بنے- فرنگی سامراج نے پاک و ہند میں جسموں کو تو غلام نہ بنایا مگر روحوں کو غلامی میں مبتلا کیا اس لئے ایسوں کے نزدیک بدن کی آزادی ہی سب کچھ ٹھہری-ایسا ہی شخص روح سے نجات کا طالب ہے اور قبر سے کہتا ہے کہ اگر خواہشاتِ بدن کے گھوڑے کی لگام شہسوارِ روح کے ہاتھ تھمانی پڑنی ہے تو میں ایسی قیامت کا مشتاق نہیں -
اس کے بعد نظم میں گو کہ صدائے غیب ہے، لیکن، یہاں قبر کا تعجب و اِستفسار پوشیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے، یہ مردہ اس قدر بیزار اور خائف کیوں ہے؟ اس بیزاری کا اصلی سبب کیا ہے؟ اس تعجب و مخفی استفسار کا جواب صدائے غیب سے ملتا ہے -
صدائےغیب
|
نے نصیبِ مار و کژدُم، نے نصیبِ دام و دَد |
نہ تو سانپ اور بچھو کے نصیب میں اور نہ ہی چوپایوں کے نصیب میں (ایسی بد ترین موت ہے- البتہ) صرف و صرف غلامی قبول کرنے والی قوموں کے مقدر میں ہے (اور وہ ہے) ابدی موت -
’’مرگِ ابد‘‘سے مراد ہے ایسی موت کہ جس کے بعد قیامت کے زلزلے سے بھی مردہ نہیں اٹھے گا، ظاہر ہے یہ ایک علامتی بات ہی ہے کہ غلامی کیسی سخت موت کا نام ہے- اقبال کے نزدیک عاقبت کے لحاظ سے حشرات الارض اور چوپائے غلامی قبول کرنے والے لوگوں سے بہتر ہیں- اقبال نے اور بھی کچھ مقامات پہ غلام ذہنیت کا جانوروں سے تقابل کیا ہے:
|
آدم از بے بصری بندگئ آدم کرد |
’’انسان نے نُورِ بصیرت سے محرومی کی وجہ سے (ملوکیّت کی) غلامی کی، اس کے پاس (آزاد رُوح کی صورت میں) قیمتی موتی تو تھا لیکن اس نے (اس کی ناقدری کرتے ہوئے) قِباد اور جمشید جیسے بادشاہوں کو دے دیا - یعنی یہ غلامی کی عادت (ملوکیّت پرستی) کی وجہ سے کتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہو گیا، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کتا کبھی دوسرے کتے کی غلامی قبول کر لے‘‘-
|
بانگِ اسرافیل اُن کو زندہ کر سکتی نہیں |
اقبال زجرو توبیخ کے انداز میں قوم کی سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غلامی کا شکار قوم کو تو اسرافیل کا صور پھونکنا بھی زندہ نہیں کر سکتا (کیونکہ) ان کا جسد تو ظاہری زندگی میں ہی روح سے خالی تھا -
اس ہمیشہ ہمیشہ کی موت کی شدت اس قدر ہے کہ اسرافیل کا صُور پھونکنا بھی ان پہ اثر نہیں کرے گا- بانگِ سرافیل سے زلزلوں کی نمودہے اگر دیکھا جائے تو حوادث و مشکلات بانگِ سرافیل بن کر گزشتہ دو اڑھائی سو برس سے مسلسل گونج رہے ہیں لیکن غلام قوم کا جسد روح سے خالی ہے، یہ بیداری کے آثار سے بھی محروم ہے -
کیا 1857ء ، اختتامِ خلافت اور اماراتِ بخارا کا انہدام بانگِ اسرافیل نہیں تھے؟ 1857ء سے لے کر آج تک 1947ء کی ہجرت، مقبوضہ جموں و کشمیر ، گجرات ، شمالی قفقاز، بلقان، چیچنیا، انڈونیشیا، الجزائر، فلسطین، کمبوڈیا، افغانستان، بوسنیا، عراق، میانمار، غزہ اور کئی دیگر خطوں میں ہونے والے قتل عام اور بنگال و قازقستان کے قحط میں مجموعی طور پہ بارہ ملین سے زائد مسلمان جاں بحق ہوئے (یہاں طوالت سے بچنے کیلئے مضمون کے اختتام پہ استعماری جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی اموات کے اعداد و شمار پہ مبنی ضمیمہ دیا گیا ہے) کیا ان میں سے ہر ہر سانحہ بانگِ اسرافیل نہیں تھا؟ لیکن ہم بطور قوم غلامی کی ذلت میں ایسے گرفتار ہوئے ہیں کہ بانگِ اسرافیل بھی ہمیں زندہ نہیں کر رہی- یعنی ہاتف غیب کی طرف سے جو سورسز اور ذرائع ہمیں بیدار کرنے کیلئے بطور بانگِ اسرافیل کے ہمیں سنائی دے رہے ہیں سننے کے با وجود ہم ان پہ کان نہیں دھر رہے - حتیٰ کہ ہم کوئی ایسا بیانیہ اور پلیٹ فارم بھی تشکیل نہیں دے سکے جس پہ اکٹھے ہو کر ہم اپنے مسائل سے اجتماعی طور پہ نبرد آزما ہو سکیں اور اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت کر سکیں -کیا اس کیفیت کو ’’مرگِ ابد‘‘ کہنے میں شاعر حق بجانب نہیں؟
جہاں تک مصرعۂ ثانی کا تعلق ہے تو رُوح کی ایک جہت تو ظاہری تعبیر پہ مبنی ہے اور دوسرے تناظر میں اسے اہلِ معارف دیکھتے ہیں - اقبال کے ہاں دونوں معانی میں اسے دیکھا جا سکتا ہے - ایک اور جہت بھی اقبالیات میں اہم ہے جو مادہ و روح کی یکتائی بمقابلہ ثنویت کی بحث سے جڑی ہے - اقبال نے اسلامی نکتہ نظر سے جدید مغربی فکر پہ تنقید کی ہے اس میں یہ نکتہ سرِ فہرست ہے کہ مغرب کے نزدیک روح مادے سے جدا کوئی چیز ہے اور یہ زندگی مادے ہی پہ مشتمل ہے اس سے آگے کچھ نہیں، بہت حد تک الحاد کا مقدمہ اسی بنیاد پہ ہی استوار ہے جزئیات و تفصیلات بالفاظ دیگر ہو سکتی ہیں- اقبال کے نزدیک اسلامی تعلیمات کے مطابق مادہ و روح میں ثنویت نہیں ہے ، مادہ روح ہی کی ایک جہت/تجلی ہے - اس لئے اقبال ’’اردشیری و جنیدی‘‘ میں یکتائی چاہتے ہیں، ’’تیغِ ایوبی و نگاہِ بایزید‘‘ کو باہم دگر پیوست دیکھتے ہیں ، فقر و سلطنت میں امتیاز کی بجائے ہم آہنگی پاتے ہوئے ’’سپاہ کی تیغ بازی و نگاہ کی تیغ بازی‘‘ کی اصطلاحیں متعارف کرواتے ہیں - اسلامی تہذیب کو مادہ و روح کی یکتائی کی وجہ ’’روشنی و گرمی‘‘ کا استعارہ کہہ کے تحسین کرتے ہیں اور مغربی تہذیب کو مادہ و مادیت پرستی ہی پہ اصرار کی وجہ سے ’’دُون‘‘ یعنی کمینہ (مادیت پرست) اور کارِ دوناں ’’حیلہ و بے شرمی‘‘ کہہ کر رد کرتے ہیں- اسلامی تہذیب روح کی نمائندہ ہے، ضربِ کلیم کی نظم ’’مدنیّتِ اسلام‘‘ میں اسلامی تمدن کے اجزاء گنواتے ہیں:
|
عناصر اِس کے ہیں؛ رُوح القدس کا ذوقِ جمال |
روح القدس کے ذوقِ جمال کی تجلیات سے منورو مزین و مسجّع تہذیب کو چھوڑ کر بالفاظِ اقبال’’کنیزِ اہرمن و دُوں نہاد و مردہ ضمیر‘‘ مغربی تہذیب کو قبول کرنے والے غلام ہی وہ لوگ ہیں کہ زندگی ہی میں ان کا جسد روح سے خالی ہو گیا تھا -
|
مر کے جی اُٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام |
گو کہ ہر ذی رُوح کی منزل قبر کی گود میں جانا ہے لیکن مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر کھڑے ہوجانا صرف آزاد لوگوں کا کام ہے -
دراصل اقبال صدیوں غلامی میں گزارنے والی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ غلامی سے نجات صرف وہی قومیں پا سکتی ہیں جن کی سوچ میں آزادی کا عنصر موجود ہوکیونکہ مر کے جی اُٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام-
مشکلات و حادثات تو ہر قوم کو در پیش ہوتے ہیں لیکن ہر آنے والی مشکل کے بعد بارِ دگر پوری توانائی سے کھڑا ہو جانا صرف آزاد لوگ ہی کر سکتے ہیں - ایک توجہ طلب پہلو مغرب کا ہے جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے - اسلام کے ظہور کے بعد مغرب کا ایک ایک نشانِ افتخار(Notion of Pride) ٹوٹتا چلا گیا-عرب عیسائیت سکڑ کر رہ گئی، نہ صرف یہ کہ مشرقی رومن ایمپائر کا عرب حصہ خلافت راشدہ کے زمانے میں مسلمانوں نے فتح کیا بلکہ بیت المقدس (یروشلم) بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا - افریقی علاقے جو نصرانی تھے یا جہاں رومن ایمپائر کی عملداری تھی وہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی- مغربی سماجی علوم کا مطالعہ رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ مغرب کے پاس دو سب سے بڑے نعرہ ہائے افتخار تھے ایک یونانی فلسفہ اور دوسری رومن ایمپائر- آج بھی اپنی تاریخ میں مغرب ان دو سے زیادہ کسی چیز پہ نہیں اتراتا، قدرت کی کیسی نصرت و تائید تھی کہ یونانی علوم بھی مسلمانوں کے مِلک ہوگئے اور رومن ایمپائر کے علاقے بھی – ’’Main land Europe‘‘ کے بہت سے علاقے بشمول اسپین، پرتگال، جنوبی اٹلی، سسلی و قریبی جزائر، سائپرس، کریٹ وغیرہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گئے، ان سے متعلقہ بحری علاقے بھی اسلامی بحریہ کے زیر اثر تھے (بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی) - (بلقان کے یورپی علاقے بہت بعد میں خلافت عثمانیہ کے وقت مسلمانوں کے ماتحت ہوئے) - صلیبی جنگوں کے آغاز 1099ء میں کیتھولک بادشاہتِ یروشلم قائم ہوئی جو کہ1244ء میں صلیبی جنگوں کے اختتام پہ سکڑ گئی اور اس کا آخری قلعہ مصری مملوک زمانے میں 1291ء میں ختم ہوا- صلیبی جنگوں کے آغاز سے کوئی ایک سو برس تک وہ احساسِ تفاخر کی جھلک دیتے تھے لیکن سلطان صلاح الدین ایُّوبی نے تھوڑی ہی مُدّت میں وہ غرور خاک میں مِلا دیا - یورپ کا آخری بڑا تفاخر مسلمانوں کے مقابلے میں مشرقی رومن ایمپائر یعنی بازنطین قسطنطنیہ رہ گیا تھا جسے کئی صدیوں کی محنت کے بعد 1453ء میں عثمانی سلطان محمد الفاتح نے فتح کر لیا - 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی سلطنتِ روم تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کے بعد اکیس سالہ نوجوان کے ہاتھوں جب اختتام کو پہنچی، تو بظاہر مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی نشانِ افتخار نہ بچا -
لیکن اس کے بعد مغرب نے بیداری کی کروٹ لی اپنے آپ کو سنبھالا، کلیسا کے متشددانہ و غیر ضروری سیاسی کردار کو لگام دیتے ہوئے فلسفہ و سائنس کو ترقی دی اور اس کے نتیجے میں دفاعی صنعت میں جدت و تیزی آئی اور اس کا سارا بخار دنیائے اسلام پہ نکالنا تاریخی عمل میں واضح ہے-آج نہ صرف یہ کہ وہ تمام ’’Notions of Pride‘‘ واپس لے چکے ہیں بلکہ ہم اس کی وہ قیمت ادا کر تے چلے جا رہے ہیں جو بنتی بھی نہیں- کیا ہمارے تاریخی عمل سے یہ واضح نہیں کہ ایک ایک نشانِ افتخار ہم سے چھنتا چلا گیا اور ہم میں ’’مر کے جی اٹھنے‘‘ کی سِکت جاتی رہی؟ مسلمانوں کا اجتماعی ردِّ عمل آزاد روحوں والا، آزاد ذہنیت والا نہیں رہا - ہر قوم پہ مشکل وقت آتا ہے، وہ ایک طرح سے موت کا مزہ چکھتی ہیں لیکن ’’ہر موت کا پوشیدہ تقاضا ہے قیامت‘‘ یعنی جی اٹھنا، پھر سے کھڑے ہو جانا ، قیّام کرنا ، زندہ و آزاد قوموں کا مشکلات کے بعد رد عمل اور ہمارے رد عمل میں آج سے نہیں اقبال کے وقت سے بہت بڑا فرق ہے تبھی تو اسے مُردۂ صد سالہ کہتے ہیں جو خاک کے ظلمت کدہ یعنی مغرب کی غلامی سے بیزار نہیں بلکہ مرنے کے بعد اٹھنے کو ذلت سمجھتا ہے -
قبر
اپنے مُردے سے
|
آہ، ظالم! تُو جہاں میں بندۂ محکوم تھا |
ہائے ئےئے! ظالم! تو دنیا میں محکوم/غلام بن کر زندہ تھا؟ مجھے یہی تو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میری مٹی دہکتا ہوا انگارہ کیوں بن گئی ہے -
یہ آہ ایسا مقام ہے جہاں ترجمے اور شرح کی بے بسی کا احساس ہوتا ہے ، اسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر بیان نہیں کیا جا سکتا - یہ آہ جو زمین نے بھری ہے یہ ایک کرب ہے، المیہ ہے، تاسف و ندامت اور اظہارِ درد و بے چارگی ہے کیا ہے؟ اسے کیا کہا جائے؟ یہ زمین کی زبان سے نکلتے ہوئے زمین کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اقبال کے قلم سے نکلتے ہوئے اقبال کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ آہ کھینچ کر سینےکے اندر اُتاری جا سکتی ہے لیکن بتائی یا توضیحی نہیں جا سکتی -
پہلے مصرعے میں صنعتِ تضاد کا عجب استعمال ہے کہ عموماً حاکم ظالم ہوتا ہے اور محکوم مظلوم ہوتا ہے، مگر اقبال محکوم کو ظالم قرار دیتے ہیں - تو وجہ واضح ہے کہ اس نے غلامی کی زنجیر پہن کر اپنی خودی ، آزادی اور اپنے ضمیر پہ ظُلم کیا ہے اور اس ظلم کا سارا ذِمہ اُس کی اپنی گردن پہ ہے- دوسرا ظلم اس نے زمین پہ کیا کہ جب سے وہ مردہ اس قبر میں لٹایا گیا زمین اذیت میں مبتلا ہوگئی وہ آگ کی طرح سلگ رہی تھی، زمین کی عزت و ناموس کا پردہ تار تار ہو گیا اور اس کے اندھیرے اور بھی گہرے ہو گئے تھے یہ اندھیرے محض خاک کی تہوں کے نہ تھے بلکہ ان میں غلامی کی لعنت کا اندھیرا سب سے اندوہ ناک تھا -
’’سوزناک‘‘ کی تشبیہ جہنم کیلئےہے یعنی قبر کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ یہ حصہ ’’دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا‘‘ کیوں بن چکا ہے؟ ارمغان حجاز ہی میں اپنی نظم ’’دوزخی کی مناجات‘‘میں ایسا مقام جو فرنگ کی غلامی میں مبتلا ہو اُسے دوزخ سے بھی بد تر جگہ قرار دیتے ہیں، مذکورہ نظم میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ایک دوزخی دوزخ کا توصیفی پہلو بیان کرتا ہے:
|
اللہ! تِرا شُکر کہ یہ خطۂ پُرسوز تیری مَیّت سے مری تاریکیاں تاریک تر |
تیری (غُلامی زدہ) میّت سے میرے اندھیرے اور بھی سیاہ ہو گئے ہیں- تیری میت نے زمین کی عزت کے پردے کو تار تار کر دیا ہے -
غلام کی میّت سے ’’زمین کا پردۂ ناموس‘‘ کیسے تار تار ہوتا ہے؟ اس بات کو اس معروف عربی مقولہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ:
’’اَلْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا‘‘ [2]
چیزیں اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہیں -
جن مقامات پہ آزاد بندے دفن کئے گئے وہاں زمین کی عزت و ناموس قائم ہوتی ہے جیسے ایک لمحے کیلئے شہدائے بدر کی قبور مبارکہ یا شہدائے اُحد کی قبور مبارکہ کا ذہن میں خیال لائیے کہ اللہ کے ان آزاد بندوں کی تدفین پہ زمین کی مسرت و شادمانی کیسی ہوگی؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے :
’’ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ‘‘[3]
’’تو مجھے قسم ہے ان مقامات کی جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں‘‘-
معروف حنفی فقیہ و مفسر ملا احمد جیون نے تفسیراتِ احمدیّہ میں کہا کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے لہٰذا ان کی قبور ان کے غروب ہونے کے مقامات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے- حکیم ترمذی ؒ نے ’’نوادر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول (ﷺ)‘‘ میں حضرت ابن عمر(رضی اللہ عنہ) سے روایت کیا ہے :
’’بے شک جب مومن مرتا ہے تو اُس کی قبر کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جاتا ہے اور قبرستان کا ہر حصہ تمنّا کرتا ہے کہ اِس (مومن) کو اُس (حصے) میں دفن کیا جائے ‘‘-
(اسی موضوع سے متعلق ضمیمہ: 1 ملاحظہ ہو)
اِس لئے صحابہ کرام (رضی اللہ عنھم) اور دیگر نیک ہستیاں جب قبر میں رکھی جاتی ہیں تو زمین اور اس کے گرد و نواح میں برکت آتی ہے جیسا کہ مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں برکت پہ قرآن کریم شاہد ہے-مفسرین کے نزدیک اس برکت کی وجہ کثرت سے انبیاء و صالحین کی قبور ہیں ، برکت سے زمین کی عزت و ناموس میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آزاد لوگ ہیں تبھی تو قبرستان کے حصے مومن کی میّت کی تمنّا کرتے ہیں -
جبکہ غلامی میں مبتلا لوگ ان کی ضد و متضاد ہیں جب ان کی نعشیں ’’آغوشِ لحد‘‘ میں آتی ہیں تو قبر کی عزت و ناموس کی چادر تار تار ہو جاتی ہے - ’’اَلْأَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا‘‘
|
الحذَر، محکوم کی مَیّت سے سو بار الحذَر |
امان! محکوم کی میّت سے سو مرتبہ امان! اے سرافیل، اے کائنات کے مالک ، اے جبرائیل!
زمین بار بار امان مانگتی ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی اَذِیّت قبر کو نہیں دی جا سکتی کہ اس میں کسی غلامی زدہ محکوم کو لا پھینکا جائے- قبر درد و کرب سے بُلبلا اٹھتی ہے کہ اے اسرافیل و جبرائیل ، اے کائنات کے مالک! میں اس تکلیف کی شدت نہیں بیان کر سکتی کہ غلام کی میّت کا میرے کسی حصے میں دفن ہونا میرے لئے کیسا کڑا اور سخت ہے -
صدائےغیب
|
گرچہ برہم ہے قیامت سے نظامِ ہست و بود |
اگرچہ قیامت سے دنیا کا نظام تہ و بالا ہوجاتا ہے ، (لیکن ایک یہی حل ہے) جس سے ’’وجود‘‘ یعنی ہونے کے چھپے ہوئے راز ظاہر ہو جاتے ہیں -
ایسے ہی مقامات ہیں جو اقبال کو اسلامی شعری روایت کے صفِ اوّل کے شعراء میں کھڑا کرتے ہیں - نظم کے اس صدائے غیب والے حصے میں معانی کے پھولوں کا جوش اس قدر شدید ہے کہ ’’اڑتے ہوئے الجھتے ہیں مُرغِ چمن کے پاؤں‘‘- جس طرح نظیرؔی نیشا پوری کے ایک شعر کو اقبال نے نقل کیا ہے کہ میرے جنگل کی کوئی لکڑی بیکار نہیں ’’چوبِ ہر نخل کہ منبر نشود ، دار کنم‘‘ کہ جس سے منبر (اُمت کی حیاتِ اجتماعی کی بات) نہ بن سکے اسے میں پھانسی گھاٹ (منصور حلاج کی طرح عارفانہ نکتہ وری کی بات) بنا دیتا ہوں- نظم کے اس بند میں ’’منبر و دار‘‘ دونوں موجود ہیں -
فلسفیانہ اعتبار سے یہاں وجود (Existence) صرف ظاہری حیات تک محدود نہیں ہے بلکہ ’’لا موجود الا اللہ‘‘ کا وہ عارفانہ منہج جو معروف کرخی سے شیخ ابن عربی اور مولانا رومی تک پہنچا ہے، اُس سے جڑا ہے - سالک پہ اکتشاف و انکشافِ حقیقت قیامت جیسے زلزلہ خیز لمحے سے عبارت ہے ، جب تک فانی پہ موت اور قیامت نہیں گزرتے یہ باقی کا قرب نہیں پا سکتا - جب خواہشات پہ موت اور نفس پہ قیامت بپا ہوگی ، تب دل کی آنکھوں کا پردہ ہٹے گا اور حقیقت کی سمجھ آئے گی - ابن عربی اور رومی نے کئی مقامات پہ بالفاظ مختلفہ یہ لکھا ہے کہ ’’تباہی تخلیق کا پیش خیمہ ہے‘‘ اور ’’فنا ہی بقا کا دروازہ ہے ‘‘-
دیگر کئی رموز و نکات کے ساتھ اس حصے کو لکھتے ہوئے شعور یا لاشعور میں ’’سرِّ حادثۂ کربلا‘‘ یعنی حضرت امام حسین (رضی اللہ عنہ) کا علمِ حریت بھی پوری طرح اقبال کی بامِ فکر پہ لہرا رہا ہے- یزید کی غاصبانہ و ناحق و غیر اسلامی حکومت اُمت کی موت تھی اور نواسۂ رسول کا اقدامِ حریت قیامت تھا، اسی اقدام سے تو احرار کو رمزِ قرآن سمجھ آئی - گرچہ قیامتِ کربلا سے نظمِ عالم درہم ہوا مگر اسی قیامت سے وجودِ امت کے اسرارِ پنہانی نمایاں ہوئے، حریت و ایمان کی وہ وادیاں جو غصب و جبر کے موسموں سے خشک ہوئی جاتی تھیں ضربِ شبّیری سے پیدا ہونے والے زلزلوں سے یقین کے چشمے پھوٹ پڑے اور سینوں کی بنجر وادیاں پھر سبزۂ ایمان و حریت سے لہلہانے لگیں - اپنے نانا جان (ﷺ) کی قوم کی حریت و احرار کی نئی تعمیر کیلئے نواسۂ رسول نے اپنا کنبہ تو قربان کروا دیا لیکن اس مشکل سے امت پہ زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا -
ان اشعار میں مجموعی خیال کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی اشیاء کو ان کی موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشتا ہے جیسا کہ سورہ الروم میں زمین کے بارے فرمان ہے :
’’فَانْظُرْ اِلٰٓی اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللہِ کَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا ط اِنَّ ذٰلِکَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰی ۚ وَ ہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ‘‘[4]
’’’پس آپ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھئے کہ وہ کس طرح زمین کو مرنے کے بعد زندہ فرما دیتا ہے بیشک وہ مُردوں کو بھی (اسی طرح) ضرور زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ‘‘-
|
زلزلے سے کوہ و دَر اُڑتے ہیں مانندِ سحاب |
زلزلے (یعنی قیامت خیزی) سے پہاڑ اور درے (مراد طرزِ کُہن) بادلوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگتے ہیں ، زلزلے سے وادیوں (کاسینہ پھٹتا ہے اور ) تازہ (حیاتِ نو بخشتے) چشمے اُبل پڑتے ہیں -
یہاں زلزلے سے مراد ’’زلزلۂ عالَمِ اَفکار‘‘ بھی ہے، اقبال کی مجموعی فکریات کی روشنی میں دیکھیں تو اقبال ایک ایسی فکری تبدیلی کی بات کرتے ہیں جو شعوری، وجودی، تہذیبی ، تاریخی حتیٰ کہ ہر ہر جہت سے دنیائے اسلام کو مثبت سمت لے جاتے ہوئے بدل کے رکھ دے اور جو ذہنی و نفسیاتی غلامی قبول کر رکھی ہے اس سے نجات دلائے -
ادبی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو کلامِ اقبال کی شاندار خاصیتوں میں ایک چیز شعری تصویر نگاری (Poetic Imagery) ہے - درج بالا شعر میں بھی اقبال نے صرف الفاظ سے ایسا متحرک اور مکمل منظر نقش کیا ہے کہ کئی متحرک تصویریں خود بخود آنکھوں میں اتر آتی ہیں - پہلے مصرعے میں اقبال نے زمین کی تہوں میں برپا ہونے والے ایک مہیب زلزلے کو اس شدت سے پیش کیا ہے کہ پہاڑ اور درے، جو عمومًا مضبوطی و استحکام کی علامت سمجھے جاتے ہیں ، گویا ہوا میں اڑتے ہوئے رُوئی کے گالے ہوں- اگلے مصرعہ پڑھتے ہی قاری کے بصری پردوں پہ ایک وادی کی تصویر ابھرتی ہے جس میں شفاف پانی کے اُبلتے ہوئے چشمے نظر آتے ہیں اور سماعتِ قلب پہ ارتعاش چھوڑتی حیاتِ تازہ کے نغمے گاتی ندیاں سُنائی دینے لگتی ہیں -
|
ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریبِ تمام |
تعمیر تو خیر ہے ہی ایک مثبت سرگرمی ، یہاں تخریب کا لفظ بھی مثبت استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں سعئ تجدید، توفیقِ حق سے نُصرتِ حق کی نیت کے ساتھ ایک نئے راستے کی تلاش، تطہیر و تزکیہ کا عمل، یا ایسی لازوال قربانی جو بظاہر تو نقصان لگے لیکن اُس کے بطن سے کُلّی خیر طلوع ہو- اِقبال کے نزدیک انقلاب، زلزلہ، موت یا تخریب وہ رُوحانی پیراڈائم شفٹ ہے جس کے بغیر تجدیدِ وجود ممکن نہیں-
یہاں صدائے غیب مکمل ہوتی ہے اور زمین غلامی و آزادی پہ اپنا اِظہارِ خیال کرتی ہے -
زمین
|
آہ یہ مرگِ دوام، آہ یہ رزمِ حیات |
افسوس اس مرگِ دوام پہ اور افسوس اِس طبقاتی کشمکش پہ ، کیا کبھی کائنات میں جاری یہ جھگڑے ختم ہونگے( یعنی حق کب ’’مہدئ بر حق‘‘ کے ذریعے) اپنا اظہار کرے گا )-
اقبال بتاتے ہیں کہ زمین ایک طرف دنیائے اسلام میں ابدی موت یعنی بد ترین غلامی کی روش پہ افسوس کرتی ہے اور دوسری طرف ’’رزمِ حیات‘‘ کے نام پہ دو باطل تعبیروں پہ افسوس کرتی ہے - ایک باطل تعبیر کارل مارکس کی ہے جس کے پیرَو جدلیاتی مادیت اور طبقاتی کشمکش کے نام پہ انسانوں سے سیاسی، سماجی، ادبی، مذہبی اور معاشی آزادیاں چھیننے کے درپئے ہیں - دوسری باطل تعبیر نطشے کی ہے جو ’’Will to power‘‘ فوق البشر اور نام و نمود کی جنگ جو ہر اخلاقی اصول سے ماوریٰ ہو سکتی ہے -
اس شعر کا دوسر امصرعہ زمین کے درد کو ظاہر کرتا ہے کہ کیا یہ کشمکشِ کائنات جو دو انتہاؤں کے درمیان ہے اس کا کوئی مبنی بر خیر اختتام بھی ہوگا یا نہیں؟
اگلے شعر کا پہلا مصرعہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ’’عقلِ محض‘‘ یا خالص مادیّت کی کوکھ سے تولد پانے والے نظریات صرف اپنے باطل معبودوں کے پجاری ہیں -
|
عقل کو ملتی نہیں اپنے بُتوں سے نجات |
عقلِ محض کو بت تراشی سے فرصت نہیں ، اہلِ ادراک بھی اور عوام بھی صرف لات و منات کے بندے بن کر رہ گئے ہیں -
مادہ پرستانہ عقل جدلیاتی مادیت کی طرز پہ روز ایک نیا بت تراشتی ہے اور بہت سے پڑھے لکھے و عام لوگ اسے خیر مان کر کورانہ تقلید میں پیچھے چل پڑتے ہیں یہ جانے بغیر کہ مٹی اور پتھر کے بتوں میں اور ’’علم و حکمت کی مُہرہ بازی‘‘ کی کھوکھلی منطق سے تراشے بتوں میں زندگی کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے ، یعنی دونوں ہی مردہ و بے جان ہیں -
|
خوار ہُوا کس قدر آدمِ یزداں صفات |
اللہ کی صفات سے متصف آدم زادہ کس قدر اپنے آپ کو رُسوا کر چکا ہے - دل اور روح پہ ایسی دنیا کا قائم رہنا ایک بوجھ بن چکا ہے -
خلیفۃ اللہ نے اپنے آپ کو اس قدر پست کیسے کر لیا؟ اس میں تو صفاتِ حق کی جلوہ گری تھی وہ اس سے کیسے محو و عدم ہوئیں؟ انسان جو کہ خود ایک مقصد تھا وہ مختلف مقاصد کا غلام کیسے ہو گیا ؟ اِسے تو ’’احسن التقویم ‘‘ بنا کر بھیجا گیا تھا اس نے خود کو ’’اسفل السافلین‘‘ تک کیسے پہنچایا؟ خالص اقبالیاتی اصطلاح میں کہا جائے تو یوں کہ اس نے اپنی خودی، اپنا ضمیر ، اپنی غیرت کیسے گنوادی ؟
حق پہ تشکیک اور حق کے اِنکار اور محض سرمائے کے اَثبات کی بنیاد پہ جو عالمی نظام (ورلڈ آرڈر) قائم کیا گیا یہ جب تک قائم ہے حقیقتاً تب تک انسانی دل اور روح پہ ایک بوجھ ہے- اس نظام کے تحت؛انسان اس دنیا میں نائبِ حق کی بجائے محض ایک ’’کنزیومر‘‘ ہے ، علم محض منافع کا ایک آلہ ہے جس کا مقصد شعور پیدا کرنا نہیں بلکہ تنخواہ کے غلام (Wage slave) پیدا کرنا ہے، اندھی طاقت کو اخلاق و بصیرت پہ فوقیّت حاصل ہے-یہ نظام اور اس کے کارندے انسان کو باطنی ارتقاء سے روکتے ہیں ، سچائی ، محبت اور وجدان کا گلہ گھونٹتے ہیں -
|
کیوں نہیں ہوتی سَحَر حضرتِ انساں کی رات؟ |
حضرتِ انسان (پہ طاری اس سیاہ) رات کی صبح کیوں نہیں ہوتی؟
یہ قاری کی مرضی ہے کہ اس مقام کو سوال سمجھے یا ترغیب سمجھے- میرے نزدیک یہ اختتامی جملہ ساری نظم کو اپنے سمیٹ کر ضمیر جھنجھوڑتا ہے اور ایک تحرک و عمل پہ اکساتا ہے کہ اے سرمائے کی رَتھ کے نیچے کچلی جانی والی پیاری سی انسانی روح! اس ظلم پہ سمجھوتہ نہ کر ، اس ظلمت کدۂ خاک سے مانوس نہ ہو ، مرگِ ابد و مرگِ دوام اختیار نہ کر ، بلکہ قیامت بپا کر، اٹھ جا! حادثات و مشکلات کی صورت میں بانگِ اسرافیل بلند ہو چکی، قیام کا وقت ہے- اس رات کو ختم ہونا ہے اٹھ اور مشرق سے روشن و تابندہ سورج کو کھینچ لا -
ضمیمہ :1
اس نظم کے مختلف الانواع محاسن میں ایک فکری حُسن یہ بھی ہے کہ قبر کا اپنی میّت سے مکالمہ کرنا کئی احادیث نبوی (ﷺ) میں بھی ذکر کیا گیا ہے- جیسا کہ سنن ترمذی کی کتاب صفۃ القیامۃ میں ایک طویل حدیث پاک ہے :
’’جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے: خوش آمدید تُو مىرى پُشْت پر چلنے والوں مىں سے مجھے محبوب ترىن تھا اور اب تُو مىرے اندر آ گىا ہے اب تُو مىرا حُسْنِ سلوک دیکھ ، پھر قبر اس کے لئے حدِ نگاہ تک کشادہ ہو جاتى ہے اور اس کیلئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے- اور (لیکن) جب کوئى فاجِر یعنی گنہگاریا کافر شخص دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے: تجھے کوئی مرحبا نہیں، تُو مىرى پشت پر چلنے والوں مىں مىرے نزدىک بدترىن شخص تھا اور اب تُو مىرے اندر آ گىا ہے- لہٰذا اب اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ پھر قبر اس پر اپنا گھىرا تنگ کر دیتی ہے اور اس کى پسلىاں اىک دوسرے مىں پىوست ہو جاتى ہىں‘‘-
اِسی طرح ایک دوسری حدیث پاک ہے جسے ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی ’’مسند‘‘ میں اور امام طبرانی نے ’’المعجم الکبیر‘‘ میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول (ﷺ) نے فرمایا :
’’جب مُردے کو قبر مىں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتى ہے: تیری خرابی ہو کىا تُو نہىں جانتا تھا مىں فتنے کا گھر ہوں، تارىکى کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں-اے انسان ! کس چیز نے تجھے مجھ سے غافل رکھا‘‘-
٭٭٭
ضمیمہ 2: مسلمانوں کے قتلِ عام کے اعداد و شمار
صاحبزادہ سُلطان احمد علی
معاون محقق: محمد بازید خان
|
نمبرشمار |
ملک / خطہ سال |
استعماریّ قوت/ظالم افواج |
شہادتیں |
|
1 |
شمالی قفقاز (سرکیشیا) |
سلطنتِ رُوسیہ 1850ء تا 1860کے عشرے میں |
تقریباً 15 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے: زیادہ تر اموات قتلِ عام، بھوک اور جلاوطنی کے باعث ہوئیں-مزید برآں، تقریباً 5 لاکھ افراد کو جلاوطن کیا گیا-[1] |
|
2 |
بلقان (بلغاریہ، سربیا، یونان، شمالی البانیا)
|
روسی اور بلقانی افواج 1877 تا 1913 اور 1912 تا 1913 |
تقریباً 14 لاکھ مسلمان قتل یا بے گھر کیے گئے-[2]
|
|
3 |
برِّصغیر پاک و ہند: علماء پر برطانوی کریک ڈاؤن |
برطانوی سلطنت |
14,000مسلم علماء کو پھانسی دی گئی-[3]
|
|
4 |
بنگال / برطانوی ہندوستان |
برطانوی سلطنت 1896 تا 1943 |
نوآبادیاتی پالیسیوں کے باعث شدید قحط پڑا جس کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ افراد جاں بحق ہوئے-[4] |
|
5 |
لیبیا |
اٹلی 1911 تا 1931 |
اٹلی کی آزادی کے دوران 80,000 سے 125,000 سے زائد لیبیائی باشندے قتل کیے گئے-[5] |
|
6 |
قازقستان (جس کے بعد سوویت یونین کا حصہ بنا) |
سوویت یونین 1930 تا 1933 |
تقریباً 15 سے 20 لاکھ نسلی قازق قحط کے باعث جاں بحق ہوئے، جو اُس وقت کی قازق آبادی کا تقریباً 30 تا 40 فیصد بنتے ہیں-[6] |
|
7 |
چیچنیا (چیچن–انگوش خودمختار سوویت سوشلسٹ جمہوریہ) |
سوویت یونین 1944 تا 1957
|
تقریباً 4 سے 5 لاکھ چیچن اور انگوش باشندوں کو جبراً وسطی ایشیا اور سائبیریا جلاوطن کیا گیا، جن میں سے 1.5 سے 2.5 لاکھ افراد سردی، بھوک اور بیماری کے باعث جاں بحق ہوگئے-[7] |
|
8 |
انڈونیشیا |
ڈچ نوآبادیاتی افواج )نیدرلینڈ( |
تقریباً 100,000 افراد قتل کیے گئے-[8] |
|
9 |
الجزائر |
فرانسیسی نوآبادیاتی فوج 1945 |
15,000 سے 45,000 تک الجزائری مسلمانوں کا قتلِ عام کیا گیا-[9] |
|
10 |
تقسیمِ ہند1947 |
برطانوی انخلا کے دوران بدانتظامی کے باعث فرقہ وارانہ فسادات |
تخمینہ ہے کہ 10 لاکھ سے زائد مسلمان قتل کیے گئے-[10] |
|
11 |
مقبوضہ جموں و کشمیر
|
بھارتی قابض فوج 1989 تا 2025 |
96,474 سے زائد افراد قتل کیے گئے، جب کہ ہزاروں لاپتہ ہوئے-[11] |
|
12 |
فلسطین (غزہ) |
اسرائیلی قابض فوج 1948 تا 2025 |
180,707 سے زائد افراد قتل کیے گئے، جن میں سے 46,707سے زائد گزشتہ 15 ماہ کے دوران جاں بحق ہوئے-[12] |
|
13 |
کمبوڈیا |
پول پاٹ کے زیرِ قیادت خمیر روج حکومت |
تقریباً 17 سے 20 لاکھ افراد قتل کیے گئے، جن میں 1 سے 5 لاکھ چام مسلمان بھی شامل تھے-[13] |
|
14 |
افغانستان |
سوویت، امریکی اور نیٹو افواج |
تقریباً 10 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے-[14] |
|
15 |
چیچنیا |
روس - 1994 تا 2000 |
3 لاکھ افراد قتل کیے گئے اور 2 لاکھ لاپتہ ہوئے-[15] |
|
16 |
بوسنیا (سریبرینیتسا) |
سربئین افواج جولائی 1995 |
8,000 مسلمان قتل کیے گئے-[16] |
|
17 |
بوسنیا و ہرزیگووِینا |
سربیئن فوج 1992 تا 1995 |
63,687 بوسنیائی مسلمان قتل کیے گئے-[17] |
|
18 |
گجرات (بھارت) |
نریندر مودی کی وزارت اعلیٰ میں بی جے پی اور دیگر ہندو انتہاپسند گروپ |
1,000 سے 2,000 مسلمان قتل کیے گئے-[18] |
|
19 |
عراق |
مغربی سربراہی میں قائم اتحاد |
تقریباً200,000 عام شہری جاں بحق ہوئے-[19] |
|
20 |
میانمار (رکھائن ریاست) |
میانمار کی فوج (2016–2017) |
مصدقہ ذرائع دستیاب نہیں-تا ہم کئی اداروں کا اندازہ ملین میں ہے- صرف 2017 میں 24,000 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے-دہائیوں پر محیط تشدد کے باعث لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے-[20] |
[1]اس اتفاق کی نشاندہی اور چند سطور سے یہ اصرار کرنا قطعاً نامناسب ہوگا کہ اقبال نے افلاطون سے استفادہ کیا ہے ، اس کے بر عکس فکری و ادبی تنقید میں بین المتونیّت (intertextuality) ایک مروّجہ اصول ہے یعنی ایک متن کے پیچھے دوسرے متون کا شعوری یا غیر شعوری عکس - یہ بات بھی بجائے خود اظہر من الشمس ہے کہ اقبال نے اسرارِ خودی میں افلاطونی فکر کو ’’گوسفندی‘‘ یعنی شیر کی بجائے بکری کا مسلک کہا ہے ، اپنے فکری اظہار میں اور بھی کئی مقامات پہ افلاطون پہ اشارتاً و کنایتاً تنقید کی ہے -
[2]( البحر الرائق شرح کنز الدقائق، امام ابن نُجیم المصری الحنفی (المتوفی: 970ھ)
[3](الواقعہ:75)
[4](الروم:50)
[1]Latypova, Leyla. “How the Circassian Genocide Remains an Inconvenient Truth for the Kremlin.” The Moscow Times, May 28 2025.
AUSIS Journal. “The Circassian Genocide: The Forgotten Tragedy of the First Modern Genocide.” (December 6, 2023). https://ausisjournal.com/2023/12/06/the-circassian-genocide-the-forgotten-tragedy-of-the-first-modern-genocide/
[2]Collège Belgique (Académie Royale de Belgique) et Université de l’Utah. Colloque: Le processus de construction de la nation dans les Balkans — Nettoyage ethnique et massacres des musulmans ottomans et turcs (1912–1913). Bruxelles: Académie Royale de Belgique, 24–25 mars 2016.
https://poli-sci.utah.edu/turkish-studies/PDF%20%20Brussels%20Conference.pdf?utm_source=chatgpt.com
[3]Ahmad, Aijaz, and Iram Aijaz. “Retribution of Muslims during Rebellion of 1857: A Case Study of Delhi and Awadh.” International Journal of Research Publication and Reviews 4, no. 6 (June 2023): 4015–4019.
[4]Puri, Kavita. “Bengal Famine: Tracking Down the Last Survivors of WWII’s Forgotten Tragedy.” BBC News, 23
February 2024. Accessed October 28, 2025. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68311520.
“Indian Famine 1896-1902.” In the Encyclopedia of Disaster Relief, SAGE Publications. Accessed October 28, 2025.
https://sk.sagepub.com/ency/edvol/disasterrelief/chpt/indian-famine-1896-1902#_
[5]Ahmida, Ali Abdullatif. Genocide in Libya: Shar, a hidden colonial history. Routledge, 2020
[6]Yale Review of International Studies. “The Kazakh Famine of 1930–1933 and Stalinist Collectivization: The Limitation of Legal Frameworks for Genocide in Communist Studies.” (Spring Issue). https://yris.yira.org/spring-issue/the-kazakh-famine-of-1930-1933-and-stalinist-collectivization-the-limitation-of-legal-frameworks-for-genocide-in-communist-studies/
[7]The Telegraph. “1944–1957: Deportation and Exile.”
https://www.telegraph.co.uk/news/1399561/1944-1957-Deportation-and-exile.html
[8]NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, “Indonesian War of Independence (1945-1949): Numbers,” accessed October 28, 2025,
[9]Charef, Abed. “The Tragedy That Paved the Way for Algerian Independence.” Rosa Luxemburg Foundation, May 8, 2024. https://www.rosalux.de/en/news/id/46481/the-tragedy-that-paved-the-way-for-algerian-independence.
Rym Bendimerad and Roqiya Sabeg, “Algeria’s War for Independence: 60 Years On,” Al Jazeera, July 5, 2022.
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/5/algerias-war-for-independence-60-years-on
[10]https://dunya.com.pk/index.php/special-edition/2022-08-14/2962
Brocklehurst, Steven. “Partition of India: ‘They Would Have Slaughtered Us.’” BBC News, August 12, 2017.
[11]Kashmir Media Service https://kmsnews.org/kms/
[12]Awad Rjoob and Gulsen Topcu. “Israel’s Occupation: 76 Years of Palestinian Tragedy.” Anadolu Agency, May 13, 2024. Accessed October 28, 2025.
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israels-occupation-76-years-of-palestinian-tragedy/3217700.
[13]Al Jazeera. “The Question of Genocide and Cambodia’s Muslims.” (November 19, 2015).
https://www.aljazeera.com/news/2015/11/19/the-question-of-genocide-and-cambodias-muslims
[14]United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict Mid-Year Update 1 January–30 June 2021. July 26 2021.
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2021_26_july.pdf.
Hamourtziadou, Lily. “How Many Iraqis Did the US Really Kill?” Asia Times, March 20, 2023.
https://asiatimes.com/2023/03/how-many-iraqis-did-the-us-really-kill/.
[15]Al Jazeera, “Official: Chechen Wars Killed 300,000,” June 26, 2005,
https://www.aljazeera.com/news/2005/6/26/official-chechen-wars-killed-300000
[16]United Nations. About the 1995 Genocide in Srebrenica. United Nations, July 11, 2024.
https://www.un.org/en/observances/srebrenica-genocide-remembrance-day.
[17]The Historiography of Genocide, Edited by Dan Stone, Professor of Modern History, Royal Holloway, University of London p. 490–493
[18]Genocide Watch. “The 2002 Gujarat Genocidal Massacres.” August 2023.
https://www.genocidewatch.com/single-post/the-2002-gujarat-genocidal-massacres.
[19]Hamourtziadou, Lily. “How Many Iraqis Did the US Really Kill?” Asia Times, March 20, 2023.
https://asiatimes.com/2023/03/how-many-iraqis-did-the-us-really-kill/.
[20]6,700 Rohingya Muslims killed in one month in Myanmar, MSF says
ttps://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/6700-rohingya-muslims-killed-in-attacks-in-myanmar-says-medecins-sans-frontieres
Myanmar army killed over 24,000 Rohingya
[1]Latypova, Leyla. “How the Circassian Genocide Remains an Inconvenient Truth for the Kremlin.” The Moscow Times, May 28 2025.
AUSIS Journal. “The Circassian Genocide: The Forgotten Tragedy of the First Modern Genocide.” (December 6, 2023). https://ausisjournal.com/2023/12/06/the-circassian-genocide-the-forgotten-tragedy-of-the-first-modern-genocide/
[1]Collège Belgique (Académie Royale de Belgique) et Université de l’Utah. Colloque: Le processus de construction de la nation dans les Balkans — Nettoyage ethnique et massacres des musulmans ottomans et turcs (1912–1913). Bruxelles: Académie Royale de Belgique, 24–25 mars 2016.
https://poli-sci.utah.edu/turkish-studies/PDF%20%20Brussels%20Conference.pdf?utm_source=chatgpt.com
[1]Ahmad, Aijaz, and Iram Aijaz. “Retribution of Muslims during Rebellion of 1857: A Case Study of Delhi and Awadh.” International Journal of Research Publication and Reviews 4, no. 6 (June 2023): 4015–4019.
https://ijrpr.com/uploads/V4ISSUE6/IJRPR14629.pdf
[1]Puri, Kavita. “Bengal Famine: Tracking Down the Last Survivors of WWII’s Forgotten Tragedy.” BBC News, 23
February 2024. Accessed October 28, 2025. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-68311520.
“Indian Famine 1896-1902.” In the Encyclopedia of Disaster Relief, SAGE Publications. Accessed October 28, 2025.
https://sk.sagepub.com/ency/edvol/disasterrelief/chpt/indian-famine-1896-1902#_
[1]Ahmida, Ali Abdullatif. Genocide in Libya: Shar, a hidden colonial history. Routledge, 2020
[1]Yale Review of International Studies. “The Kazakh Famine of 1930–1933 and Stalinist Collectivization: The Limitation of Legal Frameworks for Genocide in Communist Studies.” (Spring Issue). https://yris.yira.org/spring-issue/the-kazakh-famine-of-1930-1933-and-stalinist-collectivization-the-limitation-of-legal-frameworks-for-genocide-in-communist-studies/
[1]The Telegraph. “1944–1957: Deportation and Exile.”
https://www.telegraph.co.uk/news/1399561/1944-1957-Deportation-and-exile.html
[1]NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, “Indonesian War of Independence (1945-1949): Numbers,” accessed October 28, 2025,
[1]Charef, Abed. “The Tragedy That Paved the Way for Algerian Independence.” Rosa Luxemburg Foundation, May 8, 2024. https://www.rosalux.de/en/news/id/46481/the-tragedy-that-paved-the-way-for-algerian-independence.
Rym Bendimerad and Roqiya Sabeg, “Algeria’s War for Independence: 60 Years On,” Al Jazeera, July 5, 2022.
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/5/algerias-war-for-independence-60-years-on
[1]https://dunya.com.pk/index.php/special-edition/2022-08-14/2962
Brocklehurst, Steven. “Partition of India: ‘They Would Have Slaughtered Us.’” BBC News, August 12, 2017.
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-40849380.
[1]Kashmir Media Service https://kmsnews.org/kms/
[1]Awad Rjoob and Gulsen Topcu. “Israel’s Occupation: 76 Years of Palestinian Tragedy.” Anadolu Agency, May 13, 2024. Accessed October 28, 2025.
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israels-occupation-76-years-of-palestinian-tragedy/3217700.
[1]Al Jazeera. “The Question of Genocide and Cambodia’s Muslims.” (November 19, 2015).
https://www.aljazeera.com/news/2015/11/19/the-question-of-genocide-and-cambodias-muslims
[1]United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict Mid-Year Update 1 January–30 June 2021. July 26 2021.
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2021_26_july.pdf.
Hamourtziadou, Lily. “How Many Iraqis Did the US Really Kill?” Asia Times, March 20, 2023.
https://asiatimes.com/2023/03/how-many-iraqis-did-the-us-really-kill/.
[1]Al Jazeera, “Official: Chechen Wars Killed 300,000,” June 26, 2005,
https://www.aljazeera.com/news/2005/6/26/official-chechen-wars-killed-300000
[1]United Nations. About the 1995 Genocide in Srebrenica. United Nations, July 11, 2024.
https://www.un.org/en/observances/srebrenica-genocide-remembrance-day.
[1]The Historiography of Genocide, Edited by Dan Stone, Professor of Modern History, Royal Holloway, University of London p. 490–493
[1]Genocide Watch. “The 2002 Gujarat Genocidal Massacres.” August 2023.
https://www.genocidewatch.com/single-post/the-2002-gujarat-genocidal-massacres.
[1]Hamourtziadou, Lily. “How Many Iraqis Did the US Really Kill?” Asia Times, March 20, 2023.
https://asiatimes.com/2023/03/how-many-iraqis-did-the-us-really-kill/.
[1]6,700 Rohingya Muslims killed in one month in Myanmar, MSF says
ttps://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/6700-rohingya-muslims-killed-in-attacks-in-myanmar-says-medecins-sans-frontieres
Myanmar army killed over 24,000 Rohingya
_کی_نظم-2537.jpg)