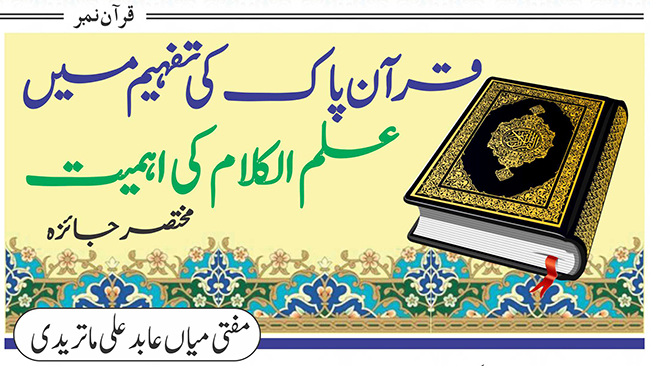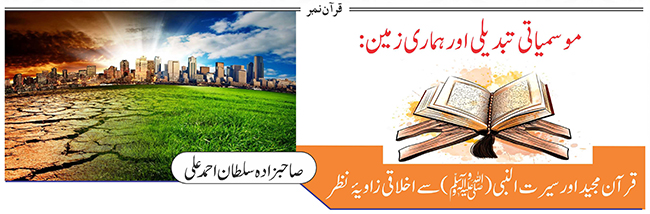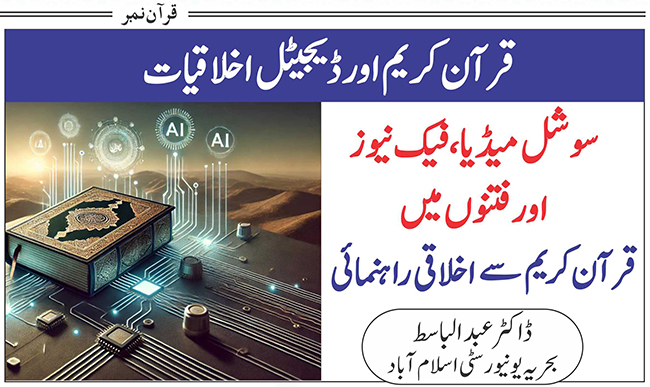ماضی قریب کی ادبی تاریخ کایہ واقعہ کتنا عجیب ہے کہ جب ناقدینِ ادب نے غزل کو عدم تسلسل اور انتشارِ خیال کے باعث نیم وحشی اور گردن زدنی قرار دیا تو قارئینِ ادب ’’بال جبریل‘‘ کی غزلیات میں اقبال کے مربوط تصورِ حیات و کائنات سے روشناس ہو چکے تھے- اقبال کی فکری وسعتوں سے ہمکنار ہونے کے بعد اب ظرف تنگنائے غزل بقدر شوق تھا- رسمی غزل کے روایتی پرستاروں کا اقبال کی جدت آفرینی سے متاثر ہونا تو محالات میں سے تھا- حیرت اس پہ ہے کہ ریزہ خیالی کو غزل کا سب سے بڑا عیب گرداننے والوں نے بھی اس نئی غزل سے بے اعتنائی برتی- نتیجہ یہ کہ جس وقت یہ لوگ محض پریشان خیالی کی بنا پر ’’غزل کی گردن بے تکلف مار دینے‘‘ کی بے ثمر جدوجہد میں مبتلا تھے، عین اس وقت اقبال کے ہاں نئی غزل، نظم سے بھی زیادہ مربوط فکر و احساس کی آئینہ دار بنتی جا رہی تھی- جب غزل سے دستکش ہو کر نظم سے وابستگی ’’بربریت کے قلمرو سے گزر کر تہذیب کی سرحد میں قدم رکھنے ‘‘کے مترادف تھی- اقبال نئے ذہن کو بار بار اپنی غزل کی طرف متوجہ کر رہے تھے :
|
میں شاخِ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبورِ عجم |
جہاں تک کلام کے خالص شاعرانہ محاسن کا تعلق ہے، اقبال حد سے بڑھے ہوئے انکسار کے خوگر ہیں-لیکن شاعری کے فکری اورعملی فیضان کی طرف اشارہ کرتے وقت اپنے ’’سوز و ساز و درد و داغ و جستجؤ و آرزو‘‘ کو ہمیشہ غزل ہی سے موسوم کرتے ہیں-یہ شاعرانہ تعلّی نہیں، اپنے معجزۂ فن پر گہرے اعتماد کا اظہار ہے-اقبال خود بھی اس بات کا شعور رکھتے تھے کہ ان کی شعری شخصیت کا حسین ترین عکس ان کی غزل میں ہے-’’بال جبریل‘‘ کی غزلیات اس وقت وجود میں آئیں، جب اقبال اپنے فنی اور فکری کمالات کے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے علاوہ خود کو دریافت کر چکے تھے-ان کی شعری شخصیت تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچ چکی تھی:
|
اسی اقبالؔ کی مَیں جُستجو کرتا رہا برسوں |
عجب اتفاق ہے کہ شخصی اور فنی نشوونما کے اوّلین مراحل میں بھی اقبال کےشاعرانہ اظہار کا وسیلہ غزل ہی تھی، اور غزل بھی بیشتر رسمی اور تقلیدی-جس وقت اقبال نے اپنا تخلیقی سفر شروع کیا، اس وقت تک اردو دنیا غالب کی عظمت اور حالی کی جدت کو دریافت نہ کر پائی تھی-پوری اردو دنیا میں داغ، امیر اور ان کے شاگردوں کی غزل کی دھوم تھی-ادبی رسائل غزلیہ مشاعروں کے ترجمان تھے، ایسے میں اگر اقبال نے عام ادبی فضاء اور عنفوانِ شباب کی ہنگامی لذتوں کے طلسم کے زیر اثر داغ سے تلمذ اور صنم خانۂ امیر کی پرستاری پر فخر کیا ہے تو کچھ عجب نہیں-تعجب اس پہ ہے کہ جب لاہور کے بازارِ حکیماں سے لے کرلکھنؤ کے خدنگ نظر کے مشاعروں تک، شاعری بندشِ زبان اور لطف محاوروں کے جھوٹے سچے تفاخر اور محبوب کے پیکر اور پیرہن سے مریضانہ لذت کے اکتساب کا دوسرا نام تھا-اقبال اس فضا میں رچ بس کر بھی اسی کے ہو کے نہ رہ گئے بلکہ انہوں نے بہت جلد اپنی راہ تراش لی:
|
اقبالؔ لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض |
یہ خمِ زلفِ کمال مشق سخن کے زمانے میں معاملہ بندی، وقوع گوئی اور رسمی تصوف کے مضامین پر دسترس سے عبارت تھا-ہر چند اس ابتدائی ادبی سیاحت کےدوران اقبال شاعرانہ صناعی اور اظہار و بیان کے مروجہ پیرایوں میں مہارت پیدا کر کے شاعری میں زبان کے اعجاز کو سمجھنے میں مصروف رہے-لیکن حسن و عشق کی روایتی توصیف اور شوخی و شرارت کی مصوری کے اس دور تقلید میں بھی جا بجا فکری تجسس کے نقوش جلوہ گر ہیں-اسی تجسس کی بدولت اقبال حیرت انگیز رفتار سے فنی ارتقا کے ابتدائی مگر کٹھن مراحل طے کرتے ہوئے بہت جلد روایتی تغزل سے انحراف کی منزل پر آپہنچے:
|
تقلید کی روِش سے تو بہتر ہے خودکُشی |
یہ شعر دورِ اول کی آخری غزل کا ہے، یہ بتانے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اقبال کی شاعری کے بعد کے ادوار کو ان کے قیام فرنگ سے کچھ یوں وابستہ کر دیا گیا ہے جیسے اقبال یورب کا سفر اختیار نہ کرتے تو ان کی شاعری رسمی شاعری کی حدود سے آگے نہ بڑھتی-اس سلسلے میں اقبال کے تَرکِ شاعری کے ارادوں اور سر عبد القادر اور پروفیسر آرنلڈ کے مشوروں کا تذکرہ بھی ضرور کیاجاتا ہے-یہ سب باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں مگر ان سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اقبال یورپ روانہ ہونے سے پیشتر وہ رسمی اور تقلیدی شاعری ترک کر چکے تھے جس نے بزمِ سخن کو بزمِ ماتم بنا رکھا تھا-جب اقبال یورپ پہنچے تو ان کے لب پر یہ صدا تھی:
|
گیا ہے تقلید کا زمانہ، مجاز رختِ سفر اُٹھائے |
یہ اقبال کے فنی سفر کا وہ موڑ ہے جہاں مجاز رخت سفر اٹھا چکا ہے اور حقیقت سے ہم کلام ہونے کے کٹھن مراحل درپیش ہیں-ایسے میں ترکِ شاعری کا ارادہ اس بات کا غمّاز ہے کہ ابھی سفر کی نئے مراحل کی دشواریوں سے عہدہ برآ ہونے کی تیاری مکمل نہیں ہو پائی-یہ عبوری دور بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور اقبال بہ اندازِ دگر غزل سرا ہوتے ہیں:
|
میں ظُلمتِ شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو |
یہ غزل اقبال کی آئندہ شاعری کا منشور ہے-آگے چل کر جو تصورات اقبال کے فکر و فن کا محور قرار پائے وہ سب اس میں موجود ہیں-ملوکیت کے استبداد اور تہذیبِ مغرب کے زوال سے لے کر سلطانیٔ جمہور کی نوید اور اس نئی دنیا کے لئے ایک نئے نظامِ فکر کی تشکیل کے لئے اپنے فنی عزائم پر اعتماد تک بہت سے تصورات، اس ایک غزل میں سمٹ آئے ہیں-یہاں مجھے خلیفہ عبد الحکیم یاد آتے ہیں جنہوں نے جہاں کہیں بھی اس غزل کا حوالہ دیا ہے اسے نظم کہا ہے-شاید اس لئے کہ یہاں نہ تو تغزل کا رسمی اور فرسودہ انداز موجود ہے اور نہ ہی غزل کی روایتی پریشاں خیالی اور عدم تسلسل کا احساس ہوتا ہے-خود اقبال نے اپنی اس نادر تخلیق کو نہ صرف ’’بانگِ درا‘‘ کے حصۂ غزلیات میں جگہ دی ہے بلکہ خلافِ معمول اس کی تخلیق کی تاریخ بھی درج کی ہے-بعد کی غزلیات پر نظم کی سی تعمیری شان اور فکری تنظیم کی چھاپ رفتہ رفتہ گہری ہونے لگتی ہے-یہ فنی عجز نہیں، اعجازِ فن ہے جس کے لئے اقبال شعوری طور پر کوشاں رہے ہیں-قیامِ فرنگ کے دوران اقبال نے جرمنی میں فلسفۂ عجم پر جو تحقیقی مقالہ تصنیف کیا تھا، اس کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں:
’’میرے خیال میں ایرانی ذہن تفصیلات کا متحمل نہیں ہو سکتا ،یہی وجہ ہے کہ اس میں اس منتظمہ کا فقدان ہے جو عام واقعات و مشاہدے سے اساسی اصول کی تفسیر کر کے ایک نظامِ تصورات کو بتدریج تشکیل دیتی ہے- ایرانیوں کا تتلی سا بیتاب تخیل گویا ایک نیم مستی کے عالم میں ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف اڑتا پھرتا ہے اور وسعتِ چمن پر مجموعی نظر ڈالنے کے ناقابل نظر آتا ہے- اس کے گہرے سے گہرے افکار و جذبات غزل کے غیرمربوط اشعار میں ظاہر ہوتے ہیں، جو اس کی فنّی لطافت کا آئینہ ہیں- برخلاف اس کے ایک برہمن اس بات کو پوری طرح محسوس کرتا ہے کہ اس کے نظریہ کو ایک مدلل نظام کی صورت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے‘‘-
عجم کے حسن طبیعت اور عرب کے سوز دروں کے پرستار اقبال کو اپنی برہمن زادگی کا فخریہ اعتراف ہے-کیا عجب تحقیق و تجسس کے دوران فارسی غزلیات میں ایرانیوں کے مابعد الطبیعی تفکر کے منتشر نقوش کی شیرازہ بندی کے کٹھن کام سے دو چار اقبال نے صنفِ غزل کو ریزہ خیالی سے نجات دلانے کی ٹھان لی ہو، اس باب میں اقبال کی کامیابی کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جب ڈاکٹر محمد صادق کو کسی ایسے فن پارے کی جستجو ہوئی جس میں زندگی سے متعلق اقبال کے مرکزی تصورات یکجا موجود ہوں تو ان کی نظر ’’بال جبریل‘‘ کی ایک غزل پر ہی آٹھہری-
اقبال کا اصل کارنامہ یہ نہیں کہ انہوں نے غزل کو اپنے مربوط اور شیرازہ بند تصورِ حیات و کائنات کی جلوہ گاہ بنایا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو قرون وسطیٰ کے تعیش، تفنن اور حیات گریز تصوف کی دھندلی اور خوابناک فضاؤں سے نکال کر عہد جدید کے فکری اور جمالیاتی مطالبات سے ہم آہنگ کیا-خدا، کائنات، آدم اور تقدیرِ آدم کے وہ تصورات جو قرون وسطیٰ کے غیر ارتقائی نظریہ کائنات اور زوال پذیر تمدن کی فکری اساس پر استوار ہو کر سکہ رائج الوقت تھے-اقبال نے انہیں فکرِ جدید کی روشنی میں یکسر بدل کر رکھ دیا اور یوں اپنے اور اپنے عہد کے فنکار کے لئے ایک نیا ذہنی پس منظر اور ایک نئی، توانا اور متحرک فکری اساس مہیا کی-غزل گو شعراء صدیوں سے حسن و عشق اور تصوف و حکمت کی جن اقدار کی پرستش میں مصروف رہے تھے، مگر جو عہد جدید میں فرسودہ ہو چکی تھیں، اقبال نے انہیں نئی اور انقلابی معنویت سے آشنا کیا-ان کے ہاں حسن و عشق جاگیردارانہ نظام کی فضا اور نفسیات کو بہت پیچھے چھوڑ کر اس مقام پر آپہنچتے ہیں جہاں عشق (زندگی) کا مقصود حسن (محبوب، خدا) میں جذب ہو کر فنا ہونا نہیں بلکہ حسن (محبوب، خدا) کو ہمیشہ اپنی ذات میں مسلسل جذب کرتے رہنا ہے-عشق فنا کا نہیں بقا کا، انتشار کا نہیں استحکام کا ضامن ہے اور مسلسل تخلیق و ارتقا کی علامت ہے کہ ’’ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں‘‘-نتیجہ یہ کہ دین و دنیا اور علم و عرفان کی دوئی مٹ جاتی ہے-انفعالی تصوف نے اسلام کے انقلابی تصورات کے اردگرد جو دھند پھیلا رکھی تھی وہ چھٹ جاتی ہے:
|
کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری خودی سے اس طلسمِ رنگ و بُو کو توڑ سکتے ہیں ٭٭٭٭٭ اگر ہو عشق تو ہے کُفر بھی مسلمانی وہ دانائے سُبل، ختم الرُّسل، مولائے کُلؐ جس نے |
غبارِ راہ، یعنی دُکھی اور پامال انسانیت میں خدا کا جلوہ نظر آنے لگتاہے-نگاہِ عشق و مستی میں یہی اول اور یہی آخر ٹھہرتی ہے اور اقبال اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے:
|
کرمکِ ناداں! طوافِ شمع سے آزاد ہو |
حسن و عشق کے ان زمین و آسمان اور زمان و مکان میں فکر و تخیل کی پرواز کے لئے جو وسعت، توانائی اور فعالیت درکار ہے، اسے اپنی ذات میں نہ پا کر اقبال کے بعض نقاد اس نئی غزل پر معترض ہوئے ہیں-بعض نے تو اسے عبد السلام ندوی کی طرح سرے سے غزل ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے-بعض فراق گورکھپوری کی طرح گو مگو کے عالم میں ہیں کہ اسے غزل کہیں یا نظم اور بعض کو وزیر آغا کی طرح یہ غزل افکار کے بوجھ تلے کراہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے-روایتی تغزل کے یہ پرستار اس نئی غزل کو زبان اور مضمون دونوں حیثیتوں سے ہدفِ تنقید بناتے ہیں:
’’غزل کی ایک خاص زبان ہے جو نرم، لطیف، شیریں ، خوشگوار اور لوچدار ہوتی ہے-ان غزلوں کی زبان ان اوصاف سے بالکل خالی ہے-غزل میں جو مضامین بیان کئے جاتے ہیں وہ خود بھی نہایت لطیف و نازک ہوتے ہیں اور یہ غزلیں اسی قسم کے لطیف مضامین سے خالی ہیں‘‘- (عبد السلام ندوی، ’’اقبال کامل‘‘)
’’اقبال نے غزل کو ایک مخصوص فلسفۂ حیات اور اندازِ نظر کےلئے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو اس سے غزل کا لوچ، دھیمی نے اور سرگوشی میں بات کرنے کا انداز قائم نہ رہ سکا‘‘- (وزیر آغا، ’’اردو شاعری کا مزاج‘‘)
’’اقبال نے غزل کے بدن اور چولے میں ایک ایسی شاعری پیش کی جو داخلی ہوتے ہوئے بھی گوشت پوست کی شاعری سے بہت دور تھی- اقبال نے غزل کےتمام اشاروں اور علامتوں کو تو لے لیا لیکن غزل کو اتنا مقصدی بنادیا کہ ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اسے غزل کہیں یا نظم‘‘- (فراق گورکھپوری، ’’نقوش‘‘ لاہور)
موہوم لطافت، مجہول نزاکت اور جسمانی احساسِ تلذذ کے پرستاروں کے یہ گلے شکوے اقبال کے روحِ معنی اور روحِ نغمہ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہیں-یہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اقبال، اقبال کیوں ہیں؟ سیماب اکبر آبادی یا نوح ناروی کیوں نہیں؟ جو شاعر اپنے عہد کے فنکار سے یہ مطالبہ کرے:
|
اے کہ اندر حجرہ ہا سازی سخن |
’’ تو کہ حجروں میں بیٹھ کر باتیں بناتا ہے کسی نمرود کے سامنے ’’لا‘‘ کا نعرہ لگا ‘‘-
اس کے ہاں نزاکت اور نغمگی کا انداز بھی نیا ہوگا-اقبال کی غزل کی منفردصوتی فضا اور نئے لب و لہجہ سے متاثر و محظوظ ہونے کے لئے اقبال ہی کے فنی معیاروں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا-اقبال غزل کی ایک خاص زبان کے قائل نہیں:
|
نہ زباں کوئی غزل کی، نہ زباں سے باخبر میں |
نہ زباں سے باخبر ہیں، کو انکسار کی بجائے اعترافِ عجر سمجھنے والوں کی بھی کمی نہیں-واقعہ یہ ہے کہ اقبال اپنے قاری کی توجہ خالص فنی تنازعات سے ہٹا کر ندرتِ افکار اور ثروتِ معانی پر مرکوز کرنا چاہتے تھے-اگر وہ زبان سے باخبر نہ ہوتے تو غزل کے ہزاروں سال پرانے علائم و رموز اور محاکات و تلازمات میں انقلاب برپا کرنے میں ہرگز کامیاب نہ ہوتے-ثبوت کے لئے ’’بالِ جبریل‘‘ کی کوئی سے غزل اٹھا لیجئے، مثلاً یہی جس کا مطلع ہے:
|
پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن |
یہاں آمد بہار کے روایتی تلازمات کی دھندلی، تاریک، گھٹی ہوئی اور یاس انگیز فضا کے مقابلے میں کشادہ، روشن اور سرور انگیز کیفیت کے علاوہ لفظوں کی ترتیب دیکھیے-یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لفظوں کو ترتیب نہیں دیا گیا، دیے جلا کر ایک قطار میں سجا دیے گئے ہیں اور پورا مصرع دیپ مالا کی طرح جگمگا اٹھا ہے-اقبال کی غزل کی عام فضا گریہ وزاری اور یاس و فسردگی کی نہیں، جوش و نشاط اور توانا رجائیت کی ہے-حسرت خیزی اور خواب ناکی کی بجائے بیداری و عمل کی ہے:
|
یہ کون غزل خواں ہے پُرسوز و نشاط انگیز |
اقبال کی غزل کے بیک وقت پر سوز و نشاط انگیز ہونے اور ان کے لب و لہجہ کی پرقوت نرمی، پرشوکت شائستگی اور باوقار جذباتی نظم و ضبط کاراز اُن کے عاشقانہ نصب العین اور فنی مسلک میں پوشیدہ ہے-بطن گیتی سے آفتابِ تازہ کی پیدائش، ایشیاء میں سحرِ فرنگیانہ کی شکست، ملوکیت و استبداد کے رد عمل میں آثارِ جنوں، اقبال کی غزل سرائی کو نشاط انگیز بناتے ہیں تو بنی نوع انسان کی وحدت اور انسانی خودی کی تعمیر میں حائل قوتوں کی کامیابی مثلاً گاندھی جی کے درسِ اخوت کے مقابلے میں مدن موہن مالوی کی نسلی برتری اور عرب عوام کی اجتماعی آرزوؤں کے مقابلے میں شریفِ مکہ کی کاروباری سازشوں کی کامیابی اسے پُر سوز بناتی ہے:
|
رِشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہَمن کا طِلسم یہی شیخِ حرم ہے جو چُرا کر بیچ کھاتا ہے حرم کے پاس کوئی اعجمی ہے زمزمہ سنج |
اقبال کا سوز بھی بڑا رجائی قسم کاہے- یہ شدید رجائیت، رقیب (انسانیت کش طاقتوں) کی اندرونی کمزوریوں کو بھانپ جانے اور اپنے زورِ بازو اور ضربتِ کاری سے اسے نیچا دکھانے کے یقین سے پھوٹتی ہے :
|
دبا رکھّا ہے اس کو زخمہور کی تیز دستی نے |
اب سوال یہ ہے کہ حسن نسوانی کی حمدوثنا اور مروجہ عشق کے روز مرہ سے کنارہ کش ہونے اور اقبال کے تصورِ زندگی کی نئی وسعتوں سے ہم کنار ہونے کے بعد غزل، غزل رہی ہے یا نظم بن گئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ نئی غزل اساسی اعتبار سے روایتی اور قدیم ہے کہ اس کی شوخی و رعنائی، قوت و توانائی، اس کا سوز و ساز اور جوش و نشاط ’’من وتو‘‘ کے ان رموز کا رَہینِ مِنّت ہے جو ہمیشہ سے غزل کی جان ہیں -اقبال نے حیات و کائنات، ارتقائے انسانی اور فطرتِ خداوندی سے متعلق اپنے انقلابی تصورات کو’’من و تو‘‘ کی کشمکشِ شوق کا پیرایہ بخش کر ان میں روایتی معاملاتِ غزل کی سی دلکشی پیدا کر دی ہے- اقبال کے اضطرابِ مسلسل کی بدولت ’’من و تو‘‘ کا مفہوم بدلتا رہتا ہے- ’’تو ‘‘کہیں انسان ہے، کہیں کائنات اور کہیں خدا- ’’مَیں‘‘ سے کبھی اقبال کی اپنی ذات مرادہے اور کبھی انسان- مناسب معلوم ہوتاہے کہ یہاں ’’بانگ درا‘‘ کی ایک غزل نما نظم ’’مَیں اور تو‘‘ کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے-فلسفہ و شعر کی نشوونما کے ابتدائی مراحل میں اقبال ’’من و تو ‘‘کا یہ تصور رکھتے تھے:
|
میں نوائے سوختہ در گُلو، تو پریدہ رنگ، رمیدہ بُو |
یہاں یاس کا رنگ غالب ہے لیکن بال جبریل تک پہنچتے پہنچتے نہ ’’میں ‘‘، حکایتِ غمِ آرزو ہے اور نہ ’’تو‘‘ حدیثِ ماتمِ دلبری ہے-اب جہاں اقبال کو اپنے فلسفہ و شعر کے فیضان اور اپنی شخصیت کی عظمت پرناز ہے:
|
مِری نوا سے ہُوئے زندہ عارف و عامی کی حق سے فرشتوں نے اقبالؔ کی غمّازی |
وہاں اقبال کا ’’تو‘‘ یعنی عام آدمی بھی پریدہ رنگ اور رمیدہ بو نہیں بلکہ ہر آن تسخیرِ حیات و کائنات میں مصروف انسان ہے:
|
تُو مردِ میداں، تُو میرِ لشکر اک تُو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں اسی روز و شب میں اُلجھ کر نہ رہ جا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید |
جہاں ’’تو‘‘ کائنات کا اشاریہ ہے، وہاں بھی ’’من و تو‘‘ کی کشمکش سے نظامِ کائنات میں انسان کی مرکزی حیثیت ہی کا اثبات ہے:
|
عالِم آب و خاک و باد! سِرِّ عیاں ہے تُو کہ مَیں کب تک رہے محکومیِ انجم میں مری خاک |
اقبال کو تسخیرِ فطرت اور تعمیرِ خودی سے گریزاں آدم کی ارزانی کا احساس بھی ہے مگر یہ احساس وہیں ظاہر ہوا ہے جہاں ’’تو‘‘ سے مراد خدا ہے-ایسے موقعوں پر ان کے لہجے میں طنز کی جو تلخی پیدا ہوجاتی ہے ، اسے ایک گستاخ بے ساختگی نے شوق و شگفتہ کر دیا ہے:
|
اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن نہ خود بیں، نَے خدا بیں نے جہاں بیں |
اس شوخی و شگفتگی کا راز اس اعتماد میں ہے جو اقبال کو انسان کی شعاعِ آرزو اور مسلسل تخلیقِ مقاصد پر ہے:
|
مری جفا طلَبی کو دعائیں دیتا ہے |
جب اقبال خدا سے اپنی ذات کی تکمیل کی آرزو کرتے ہیں تو ان کے ہاں تخلیقی شادابی اور فکری رعنائی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، کبھی تو وہ دعائیہ انداز میں شکوہ سنج ہوتے ہیں:
|
کر پہلے مجھ کو زندگیِ جاوداں عطا تُو ہے محیطِ بے کراں، میں ہُوں ذرا سی آبُجو |
اور کبھی انہیں اپنی اور اپنے عظیم انسان کی تنہائی اور بے چارگی کا احساس ستاتا ہے اور ان کی آواز میں کرب اور سرشاری، رسائی اور نارسائی کے سارے سُر یکجان ہوجاتے ہیں:
|
کلی کو دیکھ کہ ہے تشنۂ نسیمِ سحَر ٹھہر سکا نہ ہوائے چمن میں خیمۂ گُل ٭٭٭٭٭ نہیں اس کھُلی فضا میں کوئی گوشۂ فراغت ٭٭٭٭٭ یہ مُشتِ خاک، یہ صر صر، یہ وسعتِ افلاک |
قدیم غزل کے قفس و آشیاں اور سلاسل و زنداں کو اقبال نے اتنی وسعت دے دی ہے کہ ساری کائنات زنداں کی صورت اختیار کر گئی ہے اور اقبال خدا کے اس ’’ظلم‘‘ کا احساس کرتے ہیں کہ ’’اپنے لئے لامکاں میرے لئے چار سو‘‘ مظلومیت کے اس احساس سے جو سوز و سازِآرزو مندی جنم لیتا ہے وہ اقبال کی شخصیت اور شاعری کو ایک انوکھی دل کشی بخشتا ہے:
|
میری نوائے شوق سے شور حریمِ ذات میں اگر مقصودِ کُل مَیں ہُوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے |
اور یوں غزل کی روایت میں محبوب کی بجائے عاشق کی شخصیت مرکزی مقام حاصل کر لیتی ہے، یعنی اقبال کو انسان کے تخلیقی ہنگامہ ہائے نو بہ نو کے مقابلے میں شانِ خداوندی ہیچ نظر آتی ہے-
٭٭٭