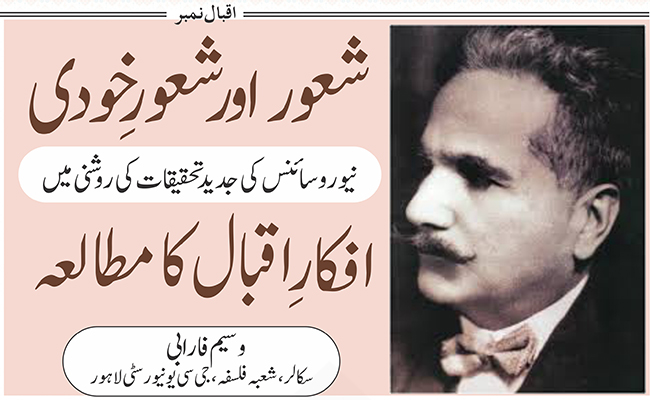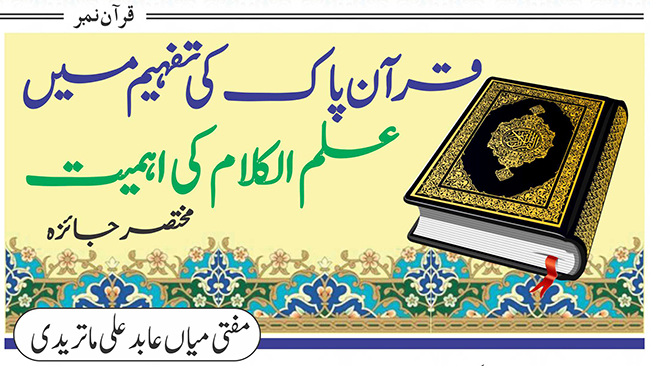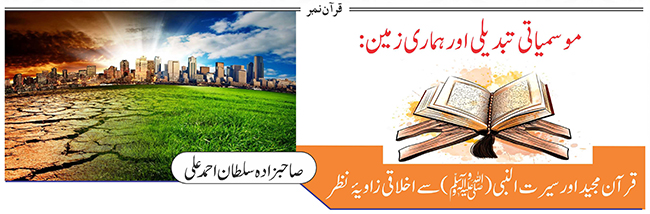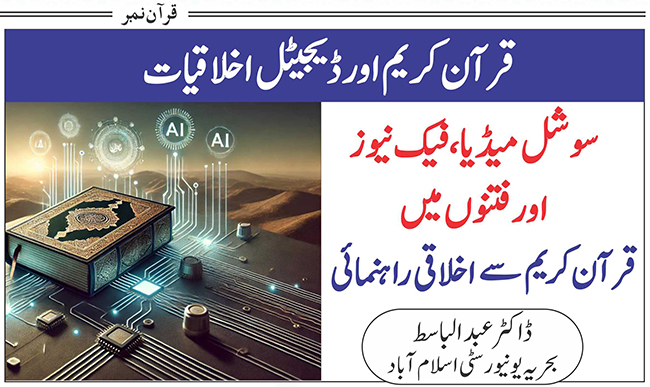ابتدائیہ:
انسان کے گوناگوں تجربات میں اگر کوئی ناقابل انکار تجربہ ہے تو وہ شعوری تجربہ ہے- انسان ہر تجربے پر شک کر سکتا ہے لیکن یہ شک نہیں کر سکتا کہ انسان کو مسلسل اپنا یا اپنے اردگرد کے ماحول کا شعور رہتا ہے جو کسی بھی لمحے رکتا نہیں- شعوری تجربے کی اس فطرت پر ہر انسان خود غور و فکر کر کے جان سکتا ہے کہ واقعی انسان کے ہر تجربے کی بنیاد شعور ہے کہ جس کے بغیر انسان کسی بھی کام کو سرانجام نہیں دے سکتا کیونکہ انسان کے تمام کارنامے اسی شعور کی بدولت ہیں-اگر شعور نہ ہو تو انسان نہ کچھ جان سکتا ہے اور نہ پہچان سکتا ہے نتیجتاً کوئی علم و دریافت ہی ممکن نہیں ہے- شعور کی اس فطرت اور انسانی زندگی میں اس کی ناگزیراہمیت کی وجہ سے صدیوں سے کئی سوالات انسانوں کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں جو کہ آج کل سائنس کی ایک شاخ نیوروسائنس کی توجہ کا مرکز ہیں- شعور کیا ہے اور شعور کی ابتدا کیا ہے؟ کیا شعور دماغ میں موجود نیورانز کی حرکت اور باہمی عمل سے پیدا ہوتا ہے یا شعور ان مادی حرکات سے ماوار ا ہے؟ کیا شعور کے ظہور کیلئے کوئی نہ کوئی محل(جیسے ہماری موجودہ صورتحال میں شعور کا محل دماغ ہے) درکار ہے یا شعور الگ سے اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس مضمون میں، شعور اور شعورِ خودی پر نیوروسائنس کی تحقیقات اور اقبال کے نظریات کا مختصر بیان اورتقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے-
1-نیوروسائنس اور شعورِ خودی:
نیورو سائنس، سائنس کی ایک شاخ ہے جو کہ دماغ اور اس کے اعصابی نظام کا مطالعہ کرتی ہے-یہ سائنس اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ اعصابی نظام کی ساخت کیسی ہے؟ اور کیسے کام کرتا ہے؟ تاکہ سمجھا جا سکے کہ یہ نظام سوچ، جذبات، رویے اور جسم کے اہم افعال کو کنٹرول کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دماغ اور اعصاب کے سائنسی مطالعے کا بنیادی محرک دماغ اور ذہن کے تعلق کو سمجھنا تھا جو کہ جدید فلسفے کا بنیادی مسئلہ رہا ہے- اس کا باقاعدہ آغاز انیسویں صدی کے اوائل میں ہوا کہ جب ایک طرف جرمن عینیت پسند فلسفہ خودی کو پروان چڑھا رہے تھے تو دوسری طرف دماغ کے سائنسی مطالعے پر کام ہورہا تھا- گزشتہ چنددہائیوں سے نیورو سائنس کی تحقیقات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے جس سے دماغ کی ساخت اور اعصابی نظام کی حرکات کا مطالعہ کرنا آسان ہو گیا ہے- ان تحقیقات کے نتیجے میں جو دریافتیں ہوئی ہیں ان میں ایک کا نام ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک (DMN) ہے جس کے افعال کو بنیاد بنا کر شعور اور شعورِ خودی سے متعلق بہت زیادہ تحقیقات کی جا رہی ہیں-
1.1-ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک (DMN):
گزشتہ چند دہائیوں تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ دماغ جب کسی بیرونی شے پر متوجہ نہیں ہوتا یا جب انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو اس وقت دماغ کا اعصابی نظام بھی متحرک نہیں ہوتا- لیکن بعد میں ہونے والے تجربات میں یہ دیکھا گیا کہ جب انسان آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو اس دوران دماغ کے چند حصوں میں خون کی سپلائی بھی معمول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے یہ مفروضہ قائم کیا گیا کہ اعصابی نظام کسی بھی وقت ساکن نہیں رہتا چاہے انسان کسی شے پر اپنی توجہ مرکوز کرے یا نہ کرے-[1] لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب انسان اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے ، اپنے اوصاف، ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے تو اس وقت دماغ کے کچھ حصے زیادہ متحرک ہوتے ہیں - جونہی انسان کسی بیرونی محرک پر متوجہ ہوتا ہے تو ان حصوں کی اعصابی حرکات میں بھی کمی آجاتی ہے-[2] اس دریافت سے دماغی حصوں کے ایک نیٹ ورک کی نشاندہی کی گئی جسے آج کل ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے-
یہ اعصابی نیٹ ورکس کا ایک گروپ ہے جو بنیادی طور پر دماغ کی پرت (cerebral cortex) کے تین حصوں پر مشتمل ہے:
1-دماغ کا اگلا درمیانی حصہ(Medial prefrontal cortex)
2-دماغ کا پچھلا درمیانی حصہ (Posterior Cingulate Cortex)
3-دماغ کا پچھلا پہلوؤں والا حصہ(Posterior parietal cortex)
یہ ایک متحرک نیٹ ورک ہے جو بچپن سے لے کر وسط عمر تک کئی مراحل سے گزرتا ہے جہاں یہ تقریباً مستحکم ہو جاتا ہے-ان تمام مراحل میں یہ نیٹ ورک انسان کے تجربات، عقائد اور سماجی روابط سے اثر پا کر تشکیل پاتا ہے جس کے نتیجے میں یہ ہر شخص میں ایک منفرد رجحان یا ذاتی شناخت کی وجہ بھی بنتا ہے-
1.2-ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کے افعال:
پچھلی دو دہائیوں سے ہونے والی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس نیٹ ورک کا انسان کے شعورِ خودی یعنی اپنے ہونے کا احساس پیدا کرنے میں ایک اہم کردار ہے- اس کے بنیادی افعال درج ذیل ہیں:
(ا)- شعورِ خودی:(Self-Consciousness)
ابتدائی تحقیقات نے یہ ثابت کیا کہ دماغ میں کچھ خاص درجے کی خودکار اندرونی سرگرمی ہر وقت موجود رہتی ہے جو پیچیدہ ذہنی عمل کو کنٹرول کرتی ہےجیسا کہ اپنے بارے میں سوچنا، مستقبل کی منصوبہ بندی-ذہن کی اس سرگرمی کو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہی کنٹرول کرتا ہے - اس کے ساتھ ساتھ یہ نیٹ ورک انسان کے مختلف تجربات کو یکجا کر کے ایک اندرونی بیانیہ تخلیق کرتا ہے جس سے انسان میں شعورِ خودی جنم لیتا ہے کہ ان تمام تجربات کو محسوس کرنے والا انسان خود ہے- اس کو محققین نے دو طرح کے طریقوں سے ثابت کیا ہے- پہلے طریقے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان بیرونی محرکات کی بجائے اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے ایک مراقبے کی حالت میں جاتا ہے تو اس دوران یہ اعصابی نیٹ ورک بہت زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور دماغ کی اس سرگرمی کا مشاہدہ PET Scanning اور fMRI جیسی ٹیکنالوجی سے کیا جاتا ہے- دوسرے طریقے میں ذہنی مریضوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے - مثلاً، شیزوفرینیا کے مریضوں میں یہ نیٹ ورک ایک صحت مند دماغ سے بہت زیادہ متحرک پایا گیا ہے اس لیے ایسے مریض بیرونی محرکات پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتے اور اپنی ذات میں گم رہتے ہیں- ان میں شعورِ خودی کی بھی کمی پائی جاتی ہے جس وجہ سے اکثر اوقات وہ اپنی پہچان ہی نہیں کر پاتے اور نہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کے ذمہ دار ہیں جو کہ شعورِ خودی کا بنیادی نکتہ ہے -[3]
(ب)-بے ساختہ ادراک(Spontaneous cognition )
اس سے مراد وہ اندرونی ذہنی سرگرمی ہے جس میں ذہن ایک شعوری حالت سے دوسری شعوری حالت میں چھلانگ لگاتا رہتا ہے اور اس دوران ذہن کسی بیرونی محرک سے مشغول نہیں ہوتا- مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز نے اس عمل کو ’’شعور کا بہاؤ‘‘ کا نام دیا تھا- ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کی دریافت کے بعد سے، اس ذہنی سرگرمی کو ذہنی آوارگی (mind-wandering) یا خیالوں میں کھو جانے (day-dreaming) سے منسلک کیا گیا ہے- بہت سے محققین نے اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ mind-wandering یا بے ساختہ ادراک کوئی بیکار اور بے فائدہ ذہنی سرگرمی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی ذہنی بیماری کی علامت ہے- درحقیقت یہ ایک نسبتاً صحت مندانہ سرگرمی ہے جو روزمرہ کے کاموں میں بھی عام طور پر پائی جاتی ہے -[4]
(ج)- معاشرتی ادراک(Social Cognition)
سماجی تعاملات اور اس کے ادراک کے دوران بھی یہ نیٹ ورک بہت زیادہ متحرک پایا گیا ہے- یہ ارد گرد کے لوگوں کی ذہنی حالتوں کی آگاہی میں فعال طور پر موجود ہوتا ہے تاکہ سماجی تعاملات کے لیے ان کے رویے کی پیش گوئی کی جا سکے اور بیانیے اور نکتہ نظر بنانے میں مدد مل سکے- نیٹ ورک اس آگاہی کو شخص اور اس کے سماجی تعاملات کی یادداشت پر انحصار کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے جبکہ بیانیہ اور نکتہ نظر تخیلاتی سوچ کے ذریعے تعمیر کیے جاتے ہیں-[5]
2-اقبال کا تصورِ خودی:
تصورِ خودی اقبال کی فکر کا مرکزی نکتہ ہے- خودی ایک زندہ حقیقت اور وجودی تجربہ ہے-اقبال کے نزدیک، انسان کے اندر ہر وقت ہونے والا شعوری تجربہ خودی کا ہی ایک فعل ہے اور اس لیے یہ خودی کے وجود پر شاہد ہے- اس کے وجود سےانکار کا مطلب انسان کے تمام کمالات اور اس کی ترقی کے امکانات سے انکار کرنا ہے- اقبال کی فکر میں خودی کا تیقن اور اثبات اتنا اہم ہے کہ وہ فرماتے ہیں:
|
منکرِ حق نزد ملا کافر است |
(ملا کے نزدیک خدا کا منکر کافر ہے لیکن میرے نزدیک اپنی خودی کا منکر کافر تر ہے)
2.1-اقبال کا طریقِ استدلال:
اقبال کے تصورِ خودی کو سمجھنے سے پہلے ، اس طریقِ فکر کا بیان کرنا ضروری ہے جو اقبال نے اس تصور کو پیش کرنے کیلئے اختیار کیا ہے- اقبال کا طریقِ استدلال فینامینولاجیکل (Phenomenological) ہے- اس طریقِ استدلال کی بنیاد انسان کا شعوری تجربہ ہے - اس طریق میں انسان اپنے شعوری تجربے کی بنیاد پر حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح حقیقت انسانی شعوری تجربے میں ظاہر ہوتی ہے- پھر اس شعوری تجربے کی بنیاد پر کچھ بنیادی اصول وضع کیے جاتے ہیں جن کا انکار کرنا انسان کیلئے نا ممکن ہو- ان اصولوں کی بنیاد پر حقیقت کے ان پہلوؤں پر بحث کی جاتی ہے جو عام طور پر انسان کے شعور پر منکشف نہیں ہوتے ہیں- اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعور کی عمومی سطح پر انسان بیرون کی اشیاء پر زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور شعوری تجربے کی گہرائی میں جانے کا خیال نہیں آتا حتیٰ کہ انسان شعوری تجربے پر توجہ ہی نہیں دیتا اور اسے محض دنیا سے تعلق بنانے کے آلے کے طور پر ہی لیتا ہے -
2.2-اقبال کا تصورِ شعور :
اقبال کے نزدیک، شعور زندگی سے متفرع ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو ایسا دائرہ نور فراہم کرے جس سے زندگی کی نمو اور ہر لمحہ آگے بڑھنے کی جستجو کو رہنمائی ملتی رہے- یہ ایک مسلسل کشمکش اور انسان کے اپنی ذات پر ہر لمحہ متوجہ ہونے کی کیفیت ہے جس کے ذریعے سے زندگی انسان کو اس کی یادوں اور دیگر تعلقات سے یک دم جدا کر کے موجودہ صورتحال پر توجہ دینے پر مجبور کرتی ہے جس پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہوتی ہے-شعور کی کوئی واضح حدود متعین نہیں ہیں اور یہ موقع کی مناسبت سے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے- [7]
اقبال کے نزدیک شعور ایک خود مختار فعالیت (Independent Activity) ہے-[8] اس شعوری تجربے کی درست تعبیر ہم پر خودی کی حقیقت آشکار کر سکتی ہے- اگر شعور کی اس خود مختار فعالیت کومکمل طورپر سمجھ لیا جائے تو تقریباً ہر خاص و عام اقبال کے اس گہرے نکتے کو سمجھ سکتا ہے جو اقبال کے تصورِ خودی کا محور ہے-شعور کی خود مختار فعالیت سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ شعور انسان کا بلا واسطہ ذاتی اور اندرونی تجربہ ہے جو کبھی رُکتا یا ٹھہرتا نہیں ہے-اقبا ل اسے زندگی کا ایک بنیادی اصول قرار دیتے ہیں- لیکن یہی شعور ایک الجھن کو جنم دیتا ہے جسے اقبال دوہرا تجربہ کہتے ہیں- اسی دوہرے تجربے کی وجہ سے انسان کو اپنی خودی یا ذات کا دوہرا شعور حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے خودی بھی شعور کی دو سطحوں پر خود کو ظاہر کرتی ہے ،فعال خودی اور بصیر خودی -[9]
2.3-فعال خودی اور بصیر خودی:
خودی اپنے فعالی رُخ کی وجہ سے اپنے سے بیرون دنیا کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے- انسان کے روزمرہ کاموں میں یہ اپنے سے بیرون دنیا پر ہی متوجہ رہتی ہے جس سے ہمارے شعور کی مختلف حالتوں کی تشکیل ہوتی ہے - شعور کی ان مختلف حالتوں کا مجموعہ انسان کی خودی پر عارضی ذات کا ایک خول چڑھا دیتا ہے جسے معاشرے کی تشکیل کردہ ذات کہا جا تا ہے- اس میں انسان کے ذاتی اور سماجی تعلقات اور ان تعلقات پر بننے والی پہچان شامل ہے- عمومی طور پر یہی معاشرے کی تشکیل کردہ ذات ہی انسان کی معاشرے میں پہچان بنتی ہے-مثلاً، جب آپ سے کوئی آپ کا تعارف پوچھتا ہے تو آپ اسے اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ در اصل معاشرے کی تشکیل کردہ ذات کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا-اس کے برعکس بصیرخودی، خودی کا وہ رُخ ہے جس کے شعوری تجربے میں، بقول اقبال، انسان حقیقتِ مطلقہ کے ساتھ رابطے میں آتا ہے- یہ شعور کی گہرائیوں میں پوشیدہ ایسی حقیقت ہے جو عام انسانی تجربے میں گم رہتی ہے- اس کی وجہ یہ ہے کہ فعال خودی، بصیر خودی پر ایک پردہ ڈال دیتی ہے جسے اقبا ل یوں بیان کرتے ہیں:
’’شعوری تجربے کا گہرا تجزیہ ہم پر نفسِ انسانی کا بصیر پہلو منکشف کرتا ہے خارجی اشیاء کے نظام میں ہماری محویت، جو ہماری موجودہ صورتحال کے لیے لازمی ہے، کے پیش نظر یہ نہایت مشکل ہے کہ ہم نفس انسانی کے بصیر پہلو کی کوئی جھلک دیکھ سکیں- خارجی اشیاء کے ساتھ مسلسل معاملات کے نتیجے میں بصیر نفس انسانی کے گرد ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور یوں ہم سے بیگانہ ہو جاتا ہے‘‘- [10]
اقبال کے اس نکتے کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ خودی کی دونوں جہتیں انسان کے شعور میں ہر وقت موجود رہتی ہیں لیکن دونوں میں فرق شعور کی سطح کا ہے- عمومی سطح پر ہمارا واسطہ صرف فعال خودی سے پڑتا ہے جبکہ بصیر خودی تک رسائی شعور کی گہرائی میں جانے سے ملتی ہے- اقبال کے نزدیک اس کا واحد طریقہ مراقبہ ہے جس میں انسان اپنے سوا ہر شے کے وجود اور اس کے خیال سے لا تعلق ہو کر صرف خود پر متوجہ ہوتا ہے- بصیر خودی تک رسائی کی اس کشمکش کو روزمرہ زندگی کی مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے - جب انسان کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتا ہے تو اسے دوہرا شعور ہوتا ہے- وہ بیک وقت صرف یہ نہیں جانتا کہ وہ سوشل میڈیا کی ریلیں دیکھ رہا ہے بلکہ وہ غیر محسوس طریقے سے اس بات سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ ریلیں دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے- لیکن انسان اتنا محو ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اس کی توجہ صرف اپنے سے جدا شے پر ہی رہتی ہے- سوچنے کی بات یہ ہے کہ ریل دیکھنے کے دوران یا کسی کام کرنے کے دوران آپ کی اپنی ذات کا شعور کہاں چلا جاتاہے؟ حیرانی کی اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اندر توجہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو آپ کے شعور کی تشکیلات کے سوا کچھ نہیں ملتا یعنی آپ کے گزرے لمحات کی یادیں، خیالات و خواہشات- سوال یہ بنتا ہے کہ پھر انسان کی ذات یا اصل کیا ہے؟ انسان کو اپنے سے باہر صرف جہان اور اس کے مظاہر ملتے ہیں اور اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسی جہان کے تشکیل کردہ تصورات ملتے ہیں جسے ہم عام طور پر اپنی ذات کہہ دہتے ہیں- یہی وہ نکتہ ہے جسے اقبال سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے مشاہدے میں تو آتا ہے لیکن ہم غور نہیں کرتے- یہی اقبال کے فلسفہ خودی کی اصل ہے جس کیلئے اقبال انسان کو اپنے شعور کی گہرائیوں میں جھانکنے پر بار بار اکساتے ہیں- یعنی اپنی خواہشات کو سمجھنا ، کسی اعلیٰ اخلاقی کسوٹی پہ پرکھنا اور ان خواہشات کی تطہیر کا عمل سر انجام دینا - اپنے شعور کے ارادوں کا درست ادراک کرنا انہیں اعلی اخلاقی منہج پہ پرکھنا اور انہیں اس ارادے اور شعورسے ہم آہنگ کرنا جو جاوید نامہ میں تیسرے گواہ کے طور پہ اقبال نے بیان کیا ہے یعنی ’’نُورِ ذاتِ حق‘‘ -
اقبال کے نزدیک خودی ایک وحدت ہے جس کا ظہور ہمارے اندرونی تجربے میں ہوتا ہے- ہمارا شعوری تجربہ دراصل خودی کا مرہونِ منت ہے- لیکن شعور میں اس کی تقسیم ہی وہ رکاوٹ ہے جو اس کی وحدت کو سمجھنے میں دشواری پیش کرتی ہے- اقبال خودی کی اس وحدت اور کلیت کے بارے میں کہتے ہیں:
’’اندرونی تجربہ خودی کا ہی عمل ہے- خودی ایک تناؤ ہے جو خودی کی ماحول پر اور ماحول کی خودی پر یلغار سے عبارت ہے- ان باہمی یلغاروں کے دوران خودی کہیں باہر موجود نہیں ہوتی بلکہ وہ سمت نما کے طور پر موجود رہتی ہے اور خود اپنے تجربے سے منظم ہوتی ہے اور تشکیل پاتی ہے‘‘- [11]
اسی نکتے کی وضاحت اقبال ایک اور جگہ یوں کرتے ہیں:
’’ لہٰذا میری حقیقی شخصیت کوئی شے (مادی چیز) نہیں بلکہ عمل(Act) سے عبارت ہے –میرا تجربہ صرف میرے اعمال کا تسلسل ہے جو ایک دوسرے سے باہم منسلک ہیں جنہیں (خودی) کی اعلیٰ مقصدیت کا رویہ ایک وحدت کی صورت میں جوڑ دیتاہے- میری تمام تر حقیقت کا انحصار (خودی کے )اس با مقصد رویے پر ہے- آپ مجھے مکان میں رکھی ہوئی کسی شے یا زمانی ترتیب رکھنے والے تجربات کے ایک مجموعے کے طور پر نہیں سمجھ سکتے- میری توجیہ، تفہیم اور تحسین کیلئے لازمی ہے کہ آپ میری تصدیقات، ارادوں، مقاصد اور خواہشات کو مدِ نظر رکھیں-[12]‘‘
3- تقابلی جائزہ:
اقبال کے تصورِ خودی اور نیوروسائنس کی تحقیقات کے تقابلی جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں چند مماثلتیں پائی جاتی ہیں لیکن امتیازات بھی اپنی جگہ قائم ہیں- دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی موجودہ صورتحال میں شعور کا محل انسانی دماغ ہے لیکن بصیر خودی کے شعور کے مرحلے پہ آ کر اقبال نے قرآنی اصطلاح کے مطابق اس کا مقام "فؤاد" بھی بیان کیا ہے جو قلب کی مزید روحانی جہت ہے - اقبال شعور کو ایک خود مختار فعالیت کہتے ہیں جبکہ نیوروسائنس اسے خودکار اندرونی سرگرمی کہتی ہے جو کہ مسلسل متحرک رہتی ہے- لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نیوروسائنس اسے دماغ کی سرگرمی سے منسوب کرتی نظر آتی ہے - نیوروسائنس نے ابھی ایساکوئی باقاعدہ دعوی نہیں کیا ہے لیکن اس وقت ہونے والی جدید بحثوں میں اس کے کئی حامی موجود ہیں جو شعور کو دماغ کی اعصابی سرگرمی سے منسوب کرتے ہیں- اقبال اس کے برعکس شعور کو زندگی کا بنیادی اصول یا وصف قرار دیتے ہیں جو 'محض دماغ کی سرگرمی' کا نتیجہ نہیں ہو سکتا-اقبال کے ہاں شعور کے بھی درجات ہیں جسے وہ شعور کے نا معلوم درجوں کا نام دیتے ہیں -[13]ہر درجے پر انسان کو حقیقت کی مزید جہات کا علم ہوتا ہے- اس لیے اقبال کہتے ہیں:
’’اس(شعور) کو اعمال مادی کے پس ِ مظہر کے طور پر بیان کرنا اس کی خود مختارانہ فعالیت سے انکار ہے اور اس کی خود مختارانہ فعالیت سے انکار کا مطلب علم کی صحت سے انکار ہے جو صرف شعور کا ہی ایک مربوط اظہار ہے‘‘-[14]
اقبال اپنی اس علمی پوزیشن میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ آج بھی کئی فلسفی بالخصوص ڈیوڈ چالمرز نیوروسائنس کی شعور پر تحقیقات کو محض شعور کے افعال پر تحقیق قرار دیتے ہیں جبکہ شعور اپنی فطرت میں محض اعصابی حرکات کا نتیجہ نہیں ہو سکتا - ان دونوں کی دلیل میں بھی بہت مماثلت پائی جاتی ہے- ڈیوڈ چالمرز کا اعتراض یہ ہے کہ نیوروسائنس شعور کے دوہرے تجربے کی صرف ایک جہت پر بات کرتی ہے جبکہ شعوری تجربے کی ذاتی جہت یعنی ہر تجربے کا لازمی جزو جس میں انسان ایک خاص قسم کے محسوس تجربے سے گزرتا ہے، وہ ابھی تک نیوروسائنس کی گرفت سے باہر ہے- اقبال بھی انسان کی ذاتی اور انفرادی جہت کو خودی کا لازمی وصف قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں:
’’دانتوں کے ڈاکٹر کو دانت درد میں مجھ سے ہمدردی ہو سکتی ہے مگر وہ میری دانت درد کا تجربہ تو نہیں کر سکتا -میری خوشیاں، تکالیف اور خواہشات خالصتاً میری ذاتی ہیں جو خالصتاً میری ذاتی خودی کی تشکیل کرتی ہیں- میرے احساسات، میری نفرتیں، محبتیں اور تصدیقات اور فیصلے خالصتاً میرے ہیں‘‘-[15]
اقبال اور نیوروسائنس اس بات پر بھی متفق ہیں کہ انسان کی خود شعوری میں معاشرے اور دماغی سرگرمی کا بہت اہم کردار ہے-نیوروسائنس کے مطابق، انسان اپنی روزمرہ زندگی میں جس خود شعوری کی بنیاد پر اپنی پہچان بناتا ہے وہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کی تشکیل کردہ ہے -یہ نیٹ ورک زیادہ متحرک بھی تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنی یادداشت پر مبنی خیالات میں محو ہوتا ہے- اس دوران انسان اپنی اس جہت پر متوجہ ہوتا ہے جو کہ معاشرے کے تعاملات سے وقت کے ساتھ ساتھ تشکیل پاتی ہے- اقبال کی فکر میں یہ فعال خودی کی سرگرمی ہے جو اپنے سے بیرون اشیاء سے تعامل سے ہمارے شعور کی مختلف حالتوں کی تشکیل کرتی ہے- دونوں کا محور شعور کی مختلف حالتیں ہے جو معاشرتی تعاملات سے جنم لیتی ہیں- لیکن اقبال اسی تشکیل کو انسان کی بصیر خودی پر ایک حجاب قرار دیتے ہیں-
اقبال کی پوزیشن اس لیے مضبوط محسوس ہوتی ہے کیونکہ اقبال انسان کی انفرادیت اور ہر تجربے میں ایک ذاتی احساس کو اہمیت دیتے ہیں جس کا انکار کرنا نا ممکن ہے- سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ نیوروسائنس جسے خود شعوری کہتی ہے اس میں بھی ایک ذاتی تجربے کا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے گزرے لمحات کو سوچ رہا ہوں- در اصل اس وقت انسان کا مفعول خودی نہیں ہوتی بلکہ خودی کی زمان و مکاں میں ہونے والی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے آثار ہوتے ہیں جو یاداشت میں محفوظ ہوتے ہیں- اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اس خود شعوری میں اگر مفعول خودی کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والے آثار ہیں تو پھر اس دوران فاعل کون ہے؟ یہ وہی نکتہ ہے جو میں اوپر واضح کر چکا ہوں کہ کس طرح بصیر خودی ہمارے عمومی شعور کی گرفت میں نہیں آتی- ہماری گرفت میں جہان آتا ہے یا جہان اور خودی کے تعامل سے پیدا ہونے والے آثار- مزید یہ کہ اگر خود شعوری محض اعصابی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے تو پھر یہ منفرد اور مخصوص قسم کا ذاتی تجربہ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ جدید فلاسفہ اسے شعور کی ہی ایسی سرگرمی کہتے ہیں جو اعصابی سرگرمیوں تک محدود نہیں کی جا سکتی جبکہ اقبال کے نزدیک اس کی بنیاد خودی کا نہ رکنے والی حرکت اور عمل ہیں جو محسوس ہونے کے باوجود شعور کی گہرائیوں میں پوشیدہ رہتی ہے- اقبال کی اس پوزیشن کا ایک ثبوت نیوروسائنس سے بھی ملتا ہے - ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک mind-wandering کے دوران سب سے زیادہ متحرک ہوتا ہے حالانکہ اس دوران انسان نہ کسی بیرونی محرک پر متوجہ ہوتا ہے اور نہ ہی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے- یہ شعور کی ایسی حالت ہے جس میں خود انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے اور اس حالت کا علم بھی تبھی ہوتا ہے جب انسان کو کوئی بیرونی محرک ڈسٹرب کرتا ہے اور وہ اس حالت سے باہر آتا ہے-
دونوں میں اہم امتیاز یہ ہے کہ اقبال شعوری تجربے کو بنیاد بناتے ہیں جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا- وہ شعوری تجربے کی ایسی تعبیر پیش کرتے ہیں جس کی فلسفیانہ جہت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے شعوری تجربے کی نوعیت واقعی ایسی ہے جیسی وہ پیش کرتے ہیں بالخصوص ان کا خودی کی انفرادیت اور ذاتی تجربے کی طرف توجہ دلانا ایک ایسا نکتہ ہے جو آج بھی زیرِ بحث ہے اور شعور کے ڈسکورس میں ایک مستند دلیل کے طور پر لیا جاتا ہے- اس کے بر عکس، نیوروسائنس کی بنیاد ایک ثانوی تجربہ ہے جس میں محض انسان کے شعوری تجربے کے دوران دماغ میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے- اس دوران انسان کن کیفیات سے گزرتا ہے یہ ابھی تک اس کی گرفت سے باہر ہے- یہاں ایک نہایت اہم مسئلہ کی تفصیل تو طوالت اختیار کر جائے گی مگر اس سے صرفِ نظر کر کے بھی نہیں گزرا جا سکتا کہ جو بات ابھی بیان ہوئی اسے عموما (hard problem of consciousness) کہا جاتا ہے اور اس وقت سائینس کیلئے یہی دردِ سر ہے- جیسے اس وقت دنیا کے معروف طبیعات دان ایڈورڈ وٹن کے مطابق ہارڈ پرابلم کبھی بھی سائنس کی ڈومین میں نہیں آ سکے گی- اس لیے نیوروسائنس اس معمہ کو حل نہیں کر سکی کہ آخر شعوری تجربے میں دماغی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص ذاتی تجربے کی کیفیت کہاں سے آتی ہے؟ اقبال اسی تجربے کو خودی سے منسوب کرتے ہیں جس کے عمل (Act) سے یہ تجربہ جنم لیتا ہے- شعور کی عام حالت اور نیوروسائنس دونوں خودی کے عمل سے جنم لینے والے اثرات پر گرفت کر پاتے ہیں جو اس کی ایک جہت ہے جبکہ خودی اپنی وحدت اور کلیت کے ساتھ شعور کی گہرائیوں میں مصروفِ عمل رہتی ہے-
نتیجہ:
فلسفہ اور سائنس دونوں شعور کی فطرت اور ابتدا کے مسئلے کو زیرِ بحث لاتے ہیں لیکن دونوں کا طریقِ کار مختلف ہے- فلسفہ شعور کی اس کلیت اور وسعت کو سامنے رکھتا ہے جس کا ادراک ہر انسان اپنے شعوری تجربے میں کرتا ہے- اس کے برعکس ، جدید نیوروسائنس کا رجحان تخفیفانہ ہے جس کے مطابق شعور دماغ کی ہی اعصابی حرکات کا نتیجہ ہے- اگرچہ کچھ فلاسفہ بھی اس نکتہ نظر کے حامی ہیں لیکن اکثریت اس تخفیفانہ رجحان کی نفی کرتے ہیں - یہی رجحان ہمیں اقبال میں ملتا ہے کہ وہ شعور کی سراسر مادی تعبیر کو نامکمل گردانتے ہیں اور مادیت و حِسّیت کے علاوہ بھی جو علم کے ذرائع ہیں ان سے استفادے پہ زور دیتے ہیں اور شعور کو زندگی کا بنیادی اصول قرار دیتے ہیں جس کی بنیاد پر انسانی علم کی عمارت استوار ہوتی ہے- یہی رویہ ہی سائنس اور فلسفے کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی مزید راہیں کھول سکتا ہے کہ تخفیفانہ راہ اختیار کرنے کی بجائے ایسی راہ اختیار کی جائے جو مسائل کی اصل نوعیت اور انفرادیت کو زائل کیے بغیر ان کا حل تلاش کرے-
٭٭٭
[1]Niels A. Lassen, David H. Ingvar, and Erik Skinhøj, "Brain Function and Blood Flow," Scientific American 239, no. 4 (October 1978): 62-71.
[2]Marcus E. Raichle, Ann M. MacLeod, Abraham Z. Snyder, William J. Powers, Debra A. Gusnard, and Gordon L. Shulman, "A Default Mode of Brain Function," Proceedings of the National Academy of Sciences 98, no. 2 (January 16, 2001): 676-682.
[3]Michael D. Greicius, Gaurav Srivastava, Allan L. Reiss, and Vinod Menon, “Default-Mode Network Activity Distinguishes Alzheimer’s Disease from Healthy Aging: Evidence from Functional MRI,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101, no. 13 (March 30, 2004): 4637–42, https://doi.org/10.1073/pnas.0308627101.
[4]Randy L. Buckner, Jessica R. Andrews-Hanna, and Daniel L. Schacter, “The Brain’s Default Network: Anatomy, Function, and Relevance to Disease,” Annals of the New York Academy of Sciences 1124, no. 1 (March 2008): 1-38,
https://doi.org/10.1196/annals.1440.011.
[5]Emily S. Finn et al., “Idiosynchrony: From Shared Responses to Individual Differences during Naturalistic Neuroimaging,” NeuroImage 215 (2020): 116828, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116828.
Yeshurun, Nguyen, and Hasson, “Default Mode Network,” 187.
[6]جاوید نامہ
[7]تجدید فکریاتِ اسلام، ص:59
[8]ایضاً
[9]تجدید فکریاتِ اسلام، ص:66
[10]تجدید فکریاتِ اسلام، ص:67
[11]تجدید فکریاتِ اسلام، ص:126
[12] تجدید فکریاتِ اسلام: ص127
[13]تجدید فکریاتِ اسلام، ص:65
[14]تجدید فکریاتِ اسلام، ص:59
[15]ایضاً: 124