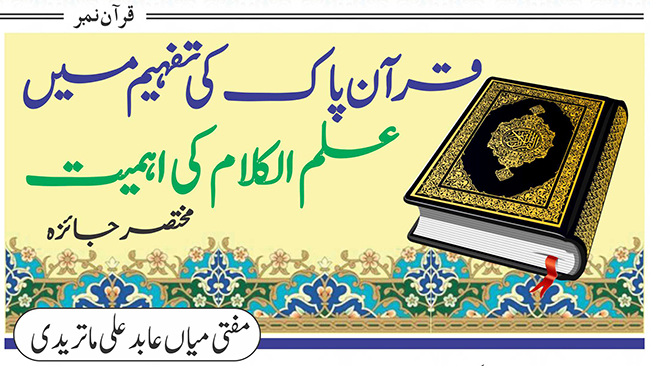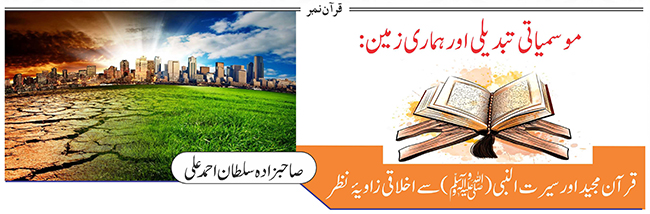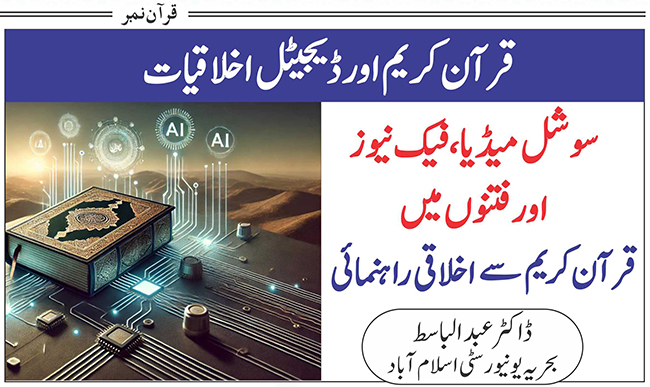ابتدائیہ:
ایسے دور میں جب مختلف آراء اور دلائل تک رسائی پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گئی ہے، یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم خیالات کو بغیر سوچے سمجھے قبول نہ کریں، بلکہ اُن کے پسِ پُشت موجود وجوہات و اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں- محض جذبات، مقبولیت یا فرقہ وارانہ رجحانات کی بنیاد پر کسی دلیل پہ ردِ عمل دینے کی بجائے اس کی منطق کو جانچنے کی صلاحیت کسی بھی معاشرے کی علمی پختگی اور فکری دیانت کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے- اگر ہم یہ صلاحیت کھو بیٹھیں، تو ہم علمی فیصلے کو محض جذباتی نعروں اور تنقیدی سوچ کو ہجوم کی رائے سے بدلنے کے خطرے سے دوچار ہو جائیں گے- تصورات اور دعوے چاہے جذبات پہ مبنی ہوں یا عمومی طور پر قبول کردہ ہوں،ان کا بنظرِ عمیق اور بغور جائزہ لینے سے ہی ایک معاشرہ اپنی اخلاقی اور علمی ساکھ برقرار رکھ سکتا ہے-
ماہِ محرم الحرام کی آمد قریب ہے اور ایسے میں ایک موضوع جو سنجیدہ غور و فکر اور منطقی جانچ کا تقاضا کرتا ہے، وہ واقعۂ کربلا ہے- یہ تاریخی واقعہ جذبات اور عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اقتدار، ذمہ داری اور انصاف جیسے اہم سوالات کو بھی جنم دیتا ہے، ایسے سوالات جو جذباتیت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ عقلی تجزیے کے بھی حقدار ہیں-
بنیادی مسئلہ:
موجودہ دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے فکری اور مذہبی مباحث کو ایک نیا چیلنج پیش کر رہی ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی دلیل دے، تقریباً ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس سے اختلاف ضرور کرے گا- مسلم دنیا میں یہ صورتحال اکثر ایک مستقل بحث کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، ایک گروہ کسی مخصوص مؤقف کا اظہار کرتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ اس کے برخلاف رائے پیش کرتا ہے- اور دونوں اپنی بات کے حق میں مختلف احکامات یا تفسیری نقطہ نظر کو بنیاد بناتے ہیں-وقت کے ساتھ، اس طرزِ فکر نے ہماری روایت کے بعض مقدس ترین پہلوؤں پر بھی سوال اٹھانے کا رجحان پیدا کر دیا ہے- ایسے سوالات کوئی بات سمجھنے کی نیت سے نہیں، بلکہ اختلافات کے ردِعمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں- ہر گزرتی نسل کے ساتھ ہم میں اس بات کی عادت بڑھ رہی ہے کہ فوراً پوچھیں:یہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے؟ اور جب کوئی بات یا اصول، قرآن کریم کے نزول کے بعد کے دور سے متعلق ہو، تو ہمارا فوری سوال ہوتا ہے ’’یہ کس نے کہا؟‘‘ اور پھر فوراً یہ جملہ آتا ہے’’مجھے ایک ایسا شخص بھی معلوم ہے جس نے اس کے برخلاف بات کی ہے‘‘-
’’رائے بازی‘‘ کا ایسا کلچر جس میں مدلل تجزیے کی کوئی پابندی نہ ہو، ہمارے دینی فہم کو صرف اس بات تک محدود کر دیتا ہے کہ کس نے کیا کہا- یہ طریقہ کار ہمیں خود سے سوچنے، منطق استعمال کرنے اور دلائل کو ان کی علمی بنیاد پر پرکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے- یہ ایک غیرسائنسی طرزِ فکر کو فروغ دیتا ہے جس میں جذبات اور وابستگیاں منطقی سوچ پر غالب آ جاتی ہیں-
اگر لوگ اسی طرح سوچنے لگیں، تو ہمیں اس خطرے کا سامنا ہو گا کہ ہم نہ صرف اجتماعی طور پر سوچنے اور ترقی کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھیں گے بلکہ اپنی اخلاقی اقدار بھی کھو دیں گے۔ حالانکہ دینی بات چیت میں ہمیں انہی چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے-
زیرِ نظر مسئلہ:
اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ جذباتی موضوعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہےجس کے متعلق بات چیت اکثر جھگڑے میں بدل جاتی ہے کہ کس نے کیا کہا - یہ حیران کن اور بلاشبہ افسوسناک بات ہے کہ آج بھی اُس روز پیش آنے والے واقعات کے بنیادی حقائق پر اختلاف موجود ہے اور ان افراد کے بارے میں بھی اختلاف ہے جن کی ذہنیت اور فیصلے اس المناک سانحے کا سبب بنے-
سب سے زیادہ زیرِ بحث رہنے والے سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ کیا یزید ، جو اس وقت کا اموی حکمران تھا، نے براہِ راست حضرت امام حسینؓ، سیدنا رسول اللہ (ﷺ) کے اہلِ بیت اور ساتھیوں کے قتل کا حکم دیا تھا؟جو بات حقیقی تاریخی تجزیے اور منطقی غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے، وہ اکثر فرقہ وارانہ اضطراب، جذباتی وابستگیوں اور نسل در نسل منتقل ہونے والی متضاد روایات کے باعث دھندلا جاتی ہے-
حقیقتاً جو بھی مضمون اس سوال کو روایتی انداز میں بیان کرتا ہے، اُسے بعض لوگ فوراً یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ ’’کسی ایک فریق کا ساتھ دیا جا رہا ہے‘‘-یہی بنیادی مسئلہ زیرِ نظر مضمون کا اصل مدعا ہے کہ ہم جو ایسے اہم تاریخی اور اخلاقی سوالات کو غیر جانبداری، عقل اور انصاف کے ساتھ دیکھنے کی بجائے، تعصب، جذبات یا موروثی سوچ کی قید میں آ کر پرکھتے ہیں- یہ مضمون کسی کا ساتھ دینے کے لئے نہیں بلکہ ایک ایسے اہم لمحے کو منطق اور علمِ سیاسیات کے اصولوں کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش ہے جو اسلامی تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے -
دلائل:
واقعۂ کربلا پر پہلے ہی معروف اور قابلِ احترام علماء کی ایک بڑی تعداد علمی کام کر چکی ہے- چونکہ اس موضوع پر موجود علمی ذخیرہ نہایت گہرا اور وسیع ہے، اس لیے محض اُن باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں جو پہلے ہی ایسے اہل علم بیان کر چکے ہیں بالخصوص جو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم سے کہیں زیادہ مستند اور ماہر ہیں-
تاہم جس چیز کی نمایاں طور پرکمی نظر آتی ہے، وہ ہے کہ واقعۂ کربلا کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟یہ بات حیران کن ہے کہ اس سانحے کی تاریخی اہمیت اور تیرہ صدیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود، آج بھی اس حقیقت کو دھندلا کر اور اختلاف کے ساتھ ظاہر کرنے کی بھر پور کوشش کی جاتی ہے کہ آیا یزید کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟
یزید کے دفاع میں عام طور پر دلیل پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ وہ دمشق میں مقیم تھا جو کہ کربلا کے میدانِ جنگ سے سینکڑوں میل دور ہے، اس لیے اسے براہِ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا- نہ تو وہ خود اموی فوج کی قیادت کے لیے موجود تھا، اور نہ ہی وہ وہاں موجود تھا کہ براہِ راست اپنے مقرر کردہ اہلکاروں، جیسے کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اموی افواج کے سالار عمر بن سعد کو احکامات دے-
ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کوئی حتمی اور مستند تحریری ثبوت موجود نہیں ہے جس میں واضح طور پر یزید نے حضرت امام حسینؓ، ان کے اہلِ خانہ اور ساتھیوں کے قتل کا براہِ راست حکم جاری کیا ہو- یزید کے حامیوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ایسا کوئی صریح حکم نامہ موجود نہیں، اس لیے یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید نے اہل بیت رسول اللہ (ﷺ) کے ساتھ اس سلوک کی منظوری دی تھی-
یہی وہ مقام ہے جہاں منطق اور علمِ سیاسیات کی بنیاد پر عمیق اور باریک بینی سے کی گئی تحقیق اور تجزیہ کی ضرورت پیش آتی ہے- زیرِ نظر مضمون میں یہی تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے -
منطق ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے؟
تاریخی احتساب کے معاملات میں، خاص طور پر جب نتائج واقعۂ کربلا جیسے سنگین ہوں، تو منطق ایک ناگزیر ذریعہ بن جاتی ہے- یہ ہمیں جذباتی پن، منتخب یادداشت اور محض فرقہ وارانہ وابستگی کی بنیاد پر روایات کو قبول یا رد کرنے کے رویوں سے بچاتی ہے-
سب سے پہلے، تحریری ثبوت کی عدم موجودگی خود بخود ذمہ داری کی عدم موجودگی کے مترادف نہیں ہے- محض اس وجہ سے کہ یزید کی طرف سے امام حسینؑ کو قتل کرنے کا کوئی براہِ راست حکم تحریری صورت میں محفوظ نہیں رہا، یہ کسی بھی عقلی معیار کے مطابق ثابت نہیں کرتا کہ ایسا کوئی حکم کبھی دیا ہی نہیں گیا تھا- قیادت، خاص طور پر ایک شخصی شاہی ریاست کے نظام میں، نہ صرف فیصلےسازی کی ذمہ دار ہوتی ہے بلکہ اختیارات کی تفویض کے نتائج کی جوابدہی بھی اسی پر عائد ہوتی ہے-
یزید کوئی غیر متعلقہ یا واقعات سے دور شخصیت نہیں تھا- وہ اموی سلطنت کا خودمختار حکمران تھا- اگر وہ حضرت امام حسینؓ اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھنا چاہتا تو وہ اس مقصد کے لیے واضح اور لازمی ہدایات جاری کر سکتا تھا- وہ یہ حکم دے سکتا تھا کہ حضرت امام حسینؓ کو گرفتار کیا جائے لیکن انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے- لیکن واقعات کا تسلسل کچھ اور ہی ظاہر کرتا ہے- سانحۂ کربلا اچانک یا حادثاتی طور پر پیش نہیں آیا بلکہ یہ سوچے سمجھے فیصلوں کے تسلسل کا نتیجہ تھا، جو یزید کے اس مطالبے سے شروع ہوا کہ حضرت امام حسینؓ اس کی بیعت کریں اور جب یہ مطالبہ رد کر دیا گیا تو اس کا انجام خونریزی پر ہوا-
یہ یزید ہی تھا جس نے کوفہ کے نرم خو گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا، جو اپنی سنگدلی اور سختی کے لیے مشہور تھا- تو یہاں پر حامیان یزید سے ایک سوال تو بنتا ہے کہ گورنر نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ بن زیاد جیسے خونخوار گورنر کو مقرر کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ امام حسین (رضی اللہ عنہ)کے تحفظ کیلئے تبدیلی کی گئی تھی ؟
یہ یزید ہی تھا جس نے اختلافِ رائے کو دبانے کے لیے طاقت کے استعمال کی اجازت دی اور یہ یزید ہی تھا جو بطور حکمران اپنے صوبائی حکمرانوں کے اقدامات پر آخری اختیار رکھتا تھا-
آئیے اس ذمہ داری کی منطقی کڑی کو نقطہ بہ نقطہ جانچتے ہیں:
یزید کے ماتحت طاقت کی مرکزیت:
یزید کو اموی حکومت پر مکمل اختیار حاصل تھا- تمام بڑے سیاسی اور عسکری فیصلے ، خاص طور پر ایسے نمایاں افراد سے متعلق جیسے کہ امام حسینؓ، جو آقا کریم (ﷺ) کے نواسے تھے، یزید کی منظوری کے بغیر ممکن نہ تھے- یہ بات ناقابلِ یقین ہے کہ حضرت امام حسینؓ جیسی عظیم شخصیت کی شہادت، جو سیاسی اور مذہبی طور پر ایک دھماکہ خیز واقعہ تھا، یزید کی مرضی یا ارادے کے بغیر ہو گیا ہو-
منطقی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ اگر یزید نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، تو پھر اس نے ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جنہوں نے یہ فعل انجام دیا؟
ابن زیاد کو مخصوص ہدایات کے ساتھ مقرر کرنا:
یزید نے کوفہ کے نسبتاً معتدل گورنر کو ہٹا کر ایک سخت گیر شخص عبید اللہ بن زیاد کو جان بوجھ کر اس عہدے پر مقرر کیا اور اسے اختلاف کرنے والوں کو کچلنے کے احکامات دیے- تاریخی روایات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ابن زیاد کو وسیع اختیارات دیے گئے تھے اور اس سے یہ توقع کی گئی تھی کہ وہ کوفہ کے لوگوں کو مکمل اطاعت پر مجبور کرے، چاہے اس کے لیے خونریزی ہی کیوں نہ کرنی پڑے- منطقی طور پر یہاں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک حکمران کسی سنگدل ماتحت کو ذمہ داری پہ مقرر کرتا ہے اور اسے اختلافِ رائے ختم کرنے کے لیے کھلے اختیارات تفویض کرتا ہے، تو پھر اس کے نتائج کی براہِ راست ذمہ داری بھی اسی حکمران پر ہی عائد ہوتی ہے-
کربلا کے سانحے کے بعد یزید کی خاموشی:
کربلا کے واقعات کے بعد یزید نے قتلِ عام کرنے والے افراد کو عہدے سے ہٹانا یا سزا دینا تو درکنار، ان کی سرزنش تک نہ کی- اس کے برعکس، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو اس کے عہدے پر برقرار رکھ کر درپردہ انعام دیا- منطقی طور پر دیکھا جائے تو ایک مطلق العنان نظام میں ظلم کے سامنے خاموشی غیر جانبداری نہیں ہوتی بلکہ یہ خاموشی واضح طور پر تائید و حمایت کے مترادف ہوتی ہے-
قیدیوں کا یزید کے دربار میں پیش کیا جانا:
شہداء کے کٹے ہوئے سر، جن میں حضرت امام حسینؓ کا سر مبارک بھی شامل تھا، دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کیے گئے، ساتھ ہی سیدنا رسول اللہ (ﷺ) کے اہلِ بیت میں سے بچ جانے والی محترم و مکرم خواتین اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر پیش کیا گیا- متعدد اور مستند اہلسنت تاریخی ذرائع یہ بیان کرتے ہیں کہ یزید نے قیدیوں کی سرِعام توہین کی اور بعض روایات کے مطابق اس نے حضرت امام حسینؓ کے سرِ مبارک کو چھڑی سے مارا اور رسول کریم (ﷺ) کے نسب کا مذاق اڑایا- اس طرح کا سلوک کسی ندامت یا افسوس کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ یہ یقیناً پہلے سے طے شدہ منظوری کا اشارہ بھی ہے، اور اس واقعہ پر یزید کی خوشنودی کو ظاہر بھی کرتا ہے-
اگرچہ کربلا کے حوالے سے جذباتی بیا نیے طویل عرصے سے غالب رہے ہیں، لیکن درحقیقت منطق جو سیاسی ڈھانچے، سٹریٹجک مفادات اور تاریخی مثالوں پر مبنی ہے، یزید کی ذمہ داری کو پختگی سے ثابت کرتی ہے- ایسے ظلم میں حکمران کے کردار کو جانچنے کے لیے دستخط شدہ حکم نامے کی ضرورت نہیں رہتی، جب نیت، فائدہ اور خاموشی اور تمسخر اڑانے کے شواہد بھرپور اور واضح ہوں-
علمِ سیاسیات کا نظریہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟
منطقی دلائل کے علاوہ، سیاسی نظریہ (Political Theory) ہمیں طاقت کے استعمال، اختیارات کے ڈھانچے اور ذمہ داری کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ایک گہرا اور منظم زاویہ فراہم کرتا ہے- سانحۂ کربلا، اگرچہ اکثر مذہبی تناظرات میں زیرِ بحث آتا ہے، تاہم وہ ایک سیاسی انتشار بھی تھا- ایسا انتشار جو ہمیں کلاسیکی اور جدید سیاسی فکر کی روشنی میں سنجیدہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے- یزید کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ہمیں یہ سوال اٹھانا ہوگا: ایسے مواقع پر خودمختار حکمران کی جوابدہی کے بارے میں ابتدائی سیاسی مفکرین ہمیں کیا بتاتے ہیں؟
میکس ویبر کی مشہور اتھارٹی کی درجہ بندی (typology of authority) روایتی، قانونی وعقلی اور کرشماتی (charismatic)، ایک مؤثر نقطۂ آغاز فراہم کرتی ہے- یزید کی حکمرانی روایتی اقتدار پر مبنی تھی، جو اسے اپنے والد حضرت امیر معاویہ (رضی اللہ عنہ) سے موروثی طور پر حاصل ہوئی - اس قسم کے نظام میں اختیار مرکز کے پاس ہوتا ہے اور نسب کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ نظام حکمران کو اپنے مقرر کردہ اہلکاروں پر مکمل کنٹرول اور ان کی جانب سے اقدام کرنے کا جواز بھی دیتا ہے- جب گورنر یا فوجی کمانڈر ایسے حکومتی ڈھانچے کے تحت کوئی فعل سرانجام دیتے ہیں، تو ان کے افعال کی حتمی ذمہ داری حکمران پر ہی عائد ہوتی ہے- یزید کے معاملے میں یہ کہنا ناقابلِ قبول ہے کہ کربلا میں ظلم ڈھانے والوں نے اس کے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا بلکہ انہوں نے ایک ایسے نظام کے تحت کام کیا جو یزید کے حکم پر قائم تھا اور اسی کی طاقت سے قائم رکھا گیا-
ہابز کے نظریۂ خودمختاری (Hobbesian Sovereignty) کے مطابق یہ ذمہ داری اور بھی واضح ہو جاتی ہے- اپنی کتاب Leviathan میں، تھامس ہابز حکمران کو قانون، اختیار اور جبر کا واحد منبع قرار دیتا ہے، جس کا بنیادی فرض طاقت کو قائم رکھنا ہوتا ہے خواہ اس کے لیے جبر کا سہارا لینا پڑے- ہابز ظلم و جبر کو جواز فراہم نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ حکمران ریاستی اقدامات کی ذمہ داری دوسروں پر نہیں ڈال سکتا - اس تناظر میں یزید کی مکمل اطاعت کے مطالبے اور اختلافِ رائے کو دبانے کی کوشش، خاص طور پر جب وہ حضرت امام حسینؓ جیسی شخصیت کے متعلق ہو، محض حکمتِ عملی نہیں بلکہ حکمران کی خودمختار اور خواہش کا اظہار ہے- جیسا کہ ہابز زور دیتا ہے، اس خودمختار ارادے کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری صرف اور صرف خود حکمران پر عائد ہوتی ہے-
پرنسپل-ایجنٹ تھیوری (Principal–Agent theory ) ایک اور اہم نظریاتی فریم ورک فراہم کرتی ہے- یہ نظریہ، جو سیاسیات اور معاشیات دونوں میں پروان چڑھا ہے، ایک سربراہ (Principal) اور اس کے ماتحتوں (Agents) کے درمیان تعلق کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ نمائندے جو سربراہ کی جانب سے عمل کرتے ہیں- جب یہ نمائندے اپنے تفویض کردہ کردار کے دائرے میں کام کرتے ہیں اور ان کے اقدامات کو سربراہ نہ مسترد کرتا ہے اور نہ ہی سزا دیتا ہے، تو ذمہ داری بالآخر سربراہ پر ہی عائد ہوتی ہے- یزید کا عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد کو مقرر کرنا، ان کے مظالم کو نہ روکنا، اور کربلا کے بعد خاموشی اختیار کرنا، یہ تمام عوامل اس نظریے پر پورا اترتے ہیں کہ یزید نے محض ان کے افعال کو برداشت ہی نہیں کیا بلکہ ان سے فائدہ بھی اٹھایا- لہٰذا ’’پرنسپل-ایجنٹ تھیوری‘‘ کے ساختیاتی اصولوں کے مطابق، یزید کی ذمہ داری و جوابدہی نہ صرف رسمی ہے بلکہ ناقابلِ تردید بھی ہے-
مکیاویلی کی حقیقت پسندی (Machiavellian Realism) اس بحث میں ایک اور جہت کا اضافہ کرتی ہے اگرچہ یہ ایک تلخ تعبیر ہے- اپنی کتاب The Prince میں، نکولو مکیاویلی اپنی معروف دلیل پیش کرتا ہے کہ حکمرانوں کو ممکنہ طور اور بعض اوقات لازماً سیاسی بقا کے لیے ظلم و ستم کا سہارا لینا پڑتا ہے- اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو یزید کا حضرت امام حسینؓ کو، جو ایک علامتی اور کرشماتی (charismatic) شخصیت کے ساتھ یزید کے مخالف تھے اور بے مثال اخلاقی جواز کے بھی حامل تھے، اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنا ایک مکیاولیائی حکمتِ عملی کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے جس کا مقصد اپنے اقتدار کی سالمیت تھا- ماورا اس سے کہ یہ تعبیر قابلِ تقلید ہے یا نہیں، یہ یزید کو اس کے اقدامات سے بری الذمہ نہیں کرتی بلکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت امام حسینؓ کا قتل ایک سوچا سمجھا منصوبہ اور سیاسی مفادات سے جڑا ہوا عمل تھا- مکیاویلی کے نظریات کی روشنی میں یزید کا یہ عمل نہ تو کوئی غلطی تھا، نہ کوئی انتظامی کوتاہی بلکہ ایک باقاعدہ سیاسی فیصلہ تھا- یہی منصوبہ بندی اس کی ذمہ داری کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ سنگین بنا دیتی ہے-
جدید سیاسی اخلاقیات، خاص طور پر ’’ذمہ داری برائے تحفظ‘‘(Responsibility to Protect – R2P) کا اصول، اس دلیل کو مزید تقویت دیتا ہے- اگرچہ یہ نظریہ جدید تعبیر ہے، لیکن اس کی بنیاد ایک ابدی اصول پر ہے کہ جنگ یا ظلم کے دوران حکمران نہ صرف اخلاقی بلکہ سیاسی طور پر بھی اُن جرائم کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو ان کے اقتدار کے تحت سرزد ہوں، چاہے وہ خود ان میں براہِ راست ملوث نہ بھی ہوں-یہ اصول ’’Command Responsibility‘‘ کے قانونی فریم ورک میں جڑا ہوا ہے، اور بین الاقوامی فوجداری عدالتوں میں اسے تسلیم کیا گیا ہے جہاں ریاستی سربراہوں کو اس بنا پر مجرم ٹھہرایا گیا کہ وہ اپنی افواج یا نمائندوں کے مظالم کو روکنے یا ان کے کئے پہ سزا دینے میں ناکام رہے- یزید، بطورِ سربراہِ ریاست، نہ صرف یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ قتل عام کو روک سکتا، بلکہ وہ ان مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لا سکتا تھا جنہوں نے یہ جرم کیا مگر اس نے نہ کچھ روکا، نہ کسی کو سزا دی- یزید کی شراکت صرف اس میں نہیں تھی جو اس نے حکم دیا، بلکہ اس میں بھی تھی جو اس نے خاموشی اور بے عملی کے ذریعے برداشت کیا-
کارل شمٹ (Carl Schmitt) کا نظریۂ خودمختاری (sovereignty) اس نکتے کو اور زیادہ واضح بنا دیتا ہے- شمٹ کے مطابق، خودمختاری کی اصل طاقت اس اختیار میں پنہاں ہے کہ حکمران یہ فیصلہ کر سکے کہ کس وقت قانون کو معطل کیا جائے اور کس کو سیاسی نظام کے تحفظ کی خاطر مستثنیٰ، سزاوار یا تباہ کر دینا ضروری ہے- امام حسین(رضی اللہ عنہ) کوشہید کرنے کا فیصلہ جو ایک ایسی شخصیت تھے جن کی اخلاقی و دینی حیثیت یزید کی سیاسی حیثیت کو براہِ راست چیلنج کر رہی تھی، عین اسی قسم کا ’’استثنائی فیصلہ‘‘ تھا- یہ نہ تو کسی جنگ کا حادثہ تھا، نہ کسی صوبائی انتظامیہ کی بدنظمی کا نتیجہ- بلکہ یہ اس وقت کے حاکم کا خودمختار فیصلہ تھا، جس کا مقصد اپنے ناجائز اقتدار کو لاحق ’’وجودی خطرے‘‘ کو ختم کرنا تھا-شمٹ کی تعبیر میں یہ عمل صرف یزید کے نام سے منسوب ہی نہیں ، بلکہ اس کی حکمرانی کا اصل مظہر تھا-
ان تمام متنوع مگر باہم جُڑے ہوئے نظریاتی رجحانات ویبر (Weber)، ہابز (Hobbes)، مکیاویلی (Machiavelli)، جدید بین الاقوامی قانون، اور کارل شمٹ (Schmitt)کو اگر یکجا کیا جائے تو وہ ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسے کسی بھی نظام میں جہاں طاقت مرکزیت رکھتی ہو اور فیصلے ایسے نمائندوں کے ذریعے نافذ کیے جائیں جو خودمختار حکمران کے علم میں اور مفاد کے تحت عمل کر رہے ہوں، تو ان فیصلوں کی مکمل ذمہ داری خود حکمران پر ہی عائد ہوتی ہے- یزید کو چاہے قدیم سیاسی فکر کے پیمانے سے دیکھا جائے، ابتدائی جدید دور کے اصولوں سے یا پھر معاصر سیاسی نظریات سے، ہر لحاظ سے کربلا میں پیش آنے والے واقعات کا ذمہ دار وہی ہے-
تنقید کا جائزہ :
کربلا کے سانحے میں یزید کی ذمہ داری پر کوئی سنجیدہ تحقیق اُس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس مؤقف کے خلاف دی جانے والی مضبوط ترین دلیلوں کا سنجیدہ تجزیہ نہ کیا جائے- علمی دیانت داری کا تقاضا صرف دعویٰ کرنے میں نہیں بلکہ ان کو مدلل اعتراضات کے خلاف جانچنے میں بھی ہے - اگرچہ یزیدپہ ذمہ داری عائد ہونے کے حق میں دلائل مضبوط اور قائل کرنے والے ہیں،تاہم ان کا موازنہ اُن عام اعتراضات سے ضرور کیا جانا چاہیے جو اس بحث میں خوارج کی جانب سے اکثر پیش کیے جاتے ہیں-
پہلا اعتراض متون کی خاموشی (textual silence) پر مبنی ہے - یعنی اس بات کا کوئی محفوظ تحریری ثبوت یا بیان موجود نہیں جس میں یزید نے واضح طور پر حضرت امام حسینؓ کے قتل کا حکم دیا ہو- قانونی اثباتیت (legal positivism) یا بین الاقوامی قانون میں رائج طریقۂ کار کی رُو سے دیکھا جائے تو کسی تحریری حکم کے بغیر نیت کو ثابت کرنا بظاہر مشکل ہوتا ہے- تاہم، پہلے بیان کیے گئے سیاسی نظریات: جیسے پرنسپل–ایجنٹ منطق (principal–agent logic) اور کمانڈ ریسپانسبلٹی (command responsibility) ،یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی جرم کی ذمہ داری کے تعین کے لیے ’’دھواں چھوڑتی بندوق‘‘ (smoking gun) یعنی براہِ راست تحریری ثبوت لازمی نہیں ہوتا- خاموش منظوری، اختیار کی ساخت اور ایسے نتائج کو روکنے میں ناکامی جن کا وقوع پذیر ہونا ممکنہ طور پر واضح تھا، یہ سب کسی سربراہ کی ذمہ داری ثابت کرنے کے لیے کافی سمجھے جاتے ہیں- آج کے بین الاقوامی جنگی جرائم کے مقدمات میں بھی متعدد حکمران صرف تحریری احکامات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنے ماتحت افراد پر کنٹرول اور ظلم کے وقت خاموشی یا بے عملی کی بنیاد پر سزا پا چکے ہیں-
دوسرا اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ذمہ داری یزید پر نہیں بلکہ اس کے ماتحت افراد، عبیداللہ بن زیاد، شمر اور عمر بن سعدپر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے ممکنہ طور پر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور جو مقامی دباؤ یا حالات کے تحت پالیسیوں کی اپنی مرضی سے تشریح کر بیٹھے- تاہم یہ دلیل یزید کے سخت مرکزیت والے طرز حکمرانی کے تناظر میں کمزور پڑ جاتی ہے- ایسے سلطنتی نظام میں جہاں خودمختار حکمران کی رائے سے اختلاف تک برداشت نہیں کیا جاتا تھا اور جہاں معاملہ حضرت امام حسینؓ جیسے اہم اور حساس شخصیت کا بیعت سے انکار کا تھا، یہ ماننا مشکل ہے کہ ایسا فیصلہ حکمران کی منظوری کے بغیر ممکن ہو سکا ہو- اس کے علاوہ، کربلا کے سانحے کے بعد یزید کا اپنے ان ماتحتوں کو سزا نہ دینا یا سرزنش تک نہ کرنا، اس دفاع کی ساکھ کو مزید کمزور کر دیتا ہے- یہ خاموشی بذاتِ خود ایک طرح کی تائید سمجھی جاتی ہے-
تیسرا اعتراض سانحۂ کربلا کے بعد کے ندامتی جذبات پر مبنی ہے- بعض تاریخی ذرائع کے مطابق، یزید نے واقعے کے بعد افسوس کا اظہار کیا یا عبید اللہ بن زیاد کو موردِ الزام ٹھہرایا، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ گمراہ کیا گیا تھا- اگرچہ یہ موقف سیاسی نفسیات کے تعمیری نظریے (constructivist view of political psychology) سے مطابقت رکھتا ہے، جس کے مطابق حکمران وقت کے ساتھ، بالخصوص اپنی ساکھ پر پڑنے والے دباؤ کے تحت، اپنے رویے میں تبدیلی لا سکتے ہیں تاہم، یہ دلیل قائل کرنے والی نہیں لگتی- اگر کوئی حکمران کسی سیاسی اقدام کے مکمل ہونے کے بعد، صرف زبانی افسوس کا اظہار کرے اور اس کے ساتھ کسی قسم کی تادیبی یا اصلاحی کارروائی نہ کرے، تو ایسی پشیمانی کا اظہار کسی بھی طرح بری الذمہ ہونے کا جواز فراہم نہیں کرتی- الفاظ، جب تک عمل کے ساتھ نہ ہوں، ذمہ داری سے فرار کا ذریعہ نہیں بن سکتے-
چوتھے اعتراض میں یہ مؤقف پیش کیا جاتا ہے کہ یزید کے اقدامات، خواہ وہ کتنے ہی افسوسناک کیوں نہ ہوں، ضروری تھے- مکیاولیائی حقیقت پسندی کے نقطۂ نظر سے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے دور میں حضرت امام حسینؓ کی تحریک کو دبانا نظم و نسق قائم رکھنے کے لیے ایک عقلی اقدام تھا- اگرچہ یہ منطق فکری طور پر ناقابلِ قبول محسوس ہوتی ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، تاہم اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ دلیل درست ہے، تب بھی یہ یزید کی ذمہ داری کو رد نہیں بلکہ الٹا تسلیم کرتی ہے- اگر کہا جائے کہ یہ تشدد ’’ضروری‘‘ تھا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عمل مکمل منصوبہ بند اور ارادی تھا- یوں، یزید کو بری الذمہ قرار دینے کے بجائے، یہ دلیل خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یزید نے مکمل سیاسی شعور اور اخلاقی نتائج کے ادراک کے ساتھ یہ فیصلہ کیا- اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا، بلکہ وہ اس کا اصل ذمہ دار ہے-
پانچواں اعتراض معیاری اضافیت (normative relativism) کا سہارا لیتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ جدید سیاسی اور قانونی معیارات جیسے ’’کمانڈ ریسپانسبیلٹی‘‘ اور ’’ذمہ داری برائے تحفظ‘‘ (Responsibility to Protect - R2P) کو ساتویں صدی کے تناظر پر لاگو کرنا درست نہیں- اگرچہ تاریخی اضافیت (historical relativism) ایک اہم تحقیقی نقطۂ نظر ہے، لیکن یہ اس آفاقی اصول کو ختم نہیں کر سکتی کہ ’’ذمہ داری ہمیشہ اختیار کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے‘‘- حتیٰ کہ ابتدائی اسلامی مصادر اور روایات میں بھی ظالمانہ حکومت کی مذمت کی گئی اور خلفاء کی اخلاقی جواب دہی کو تسلیم کیا گیا-رسول اللہ (ﷺ) کے پیارے نواسے اور خاندان کا قتل کوئی معمولی یا متنازعہ واقعہ نہ تھا- یہ اپنے ہی دور میں ایک سنگین اخلاقی گراوٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا-
آخر میں، بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کربلا کے واقعات اتنے انتشار کا شکار تھے کہ کسی ایک فرد پر واضح طور پر ذمہ داری ڈالنا مشکل ہے- وہ اس وقت کی منتشر قبائلی سیاست، ناقص مواصلاتی نظام اور غیر مرکزی حکمرانی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں- اگرچہ غیر متوقع حالات لمحاتی الجھن پیدا کر سکتے ہیں، مگر وہ قائم شدہ اختیارات کی زنجیر کو ختم نہیں کرتے، یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا، جس نے آگے عمر ابن سعد کو بھیجا- شہداء کے سروں اور اسیرانِ اہل بیتؓ کی دمشق میں یزید کے دربار میں پیشی اور اس کے بعد یزید کی خاموشی یا طمانیت، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کنٹرول ختم نہیں ہوا تھا بلکہ پوری طرح موجود تھا- حقیقت یہ ہے کہ جب حالات انتشار کا شکار ہوں، تب ہی قیادت کی اخلاقی ذمہ داری اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ نہیں کہا سکتا کہ یزید ناکام رہا بلکہ یزید جو چاہتا تھا وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب رہا -
مجموعی طور پر، ان تمام اعتراضات میں سے کوئی بھی بنیادی دلیل کو باطل نہیں کر پاتا- اکثر اعتراضات یزید کی شمولیت سے انکار نہیں کرتے بلکہ اس سے توجہ ہٹانے، اسے جواز دینے، یا تاریخی نسبت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں- تاہم، سیاسی اقتدار، تاریخی نظائر اور اخلاقی ذمہ داری کے تناظر میں دیکھا جائے تو یزید کی شراکتِ جرم کا مقدمہ مضبوطی سے قائم رہتا ہے- جب اس معاملے کو صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ سیاسی فکر اور اخلاقی منطق کے اصولوں پر پرکھا جائے، تو ذِمہ دارایءِ کربلا کے نشانات بلا شبہ یزید کے تخت کو ہی جاتے ہیں -
اختتامیہ:
کربلا کا سانحہ صرف غم اور شہادت کی داستان ہی نہیں، بلکہ یہ سیاسی اقتدار، اخلاقی ناکامی اور حکمرانی کی ذمہ داری کا ایک زندہ مطالعہ ہے- اگرچہ تاریخی بیانیے مختلف ہو سکتے ہیں اور جذباتی وابستگیاں فیصلہ سازی کو متاثر کر سکتی ہیں، مگر منطق اور علمِ سیاسیات کے نظریات ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں جس پر ذمہ داری کا تعین کیا جا سکتا ہے- یزید، ایک مرکزیت یافتہ اور درجہ بندی پر مبنی خلافت کا حکمران ہونے کے ناطے، حضرت امام حسینؓ، ان کے اہلِ خانہ اور اصحاب کے قتل کو روکنے کی مکمل طاقت رکھتا تھا- اس کا ایسا نہ کرنا، دانستہ طور پہ تقرری کے فیصلے، سانحہ کے بعد خاموشی اور اس واقعے سے حاصل ہونے والا سیاسی فائدہ، اسے ایک غیر متعلق تماشائی نہیں بلکہ اس المیے کا ذمہ دار بناتے ہیں- چاہے وہ ویبر کے اقتدار کا نظریہ ہو، ہابز کی خودمختاری، جدید پرنسپل-ایجنٹ تھیوری ہو یا ’’کمانڈ ریسپانسیبلٹی‘‘ کا بین الاقوامی اصول، نتیجہ ایک ہی رہتا ہے کہ سانحہ کربلا کی ذمہ داری کا بوجھ یزید کے کندھوں پر ہے- اس حقیقت سے انکار، تاریخی غیر جانب داری کو بچانے کی کوشش نہیں، بلکہ ان اصولوں سے انحراف ہے جن کی بنیاد پر طاقت اور انصاف کو لازمی طور پہ پرکھا جانا چاہیئے-
٭٭٭