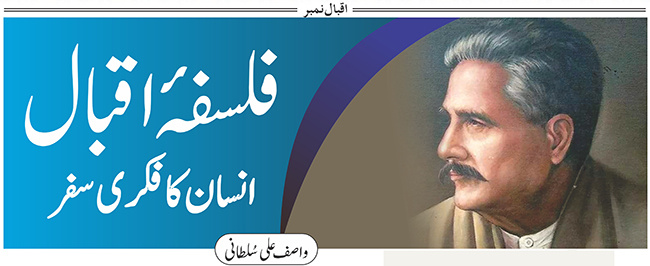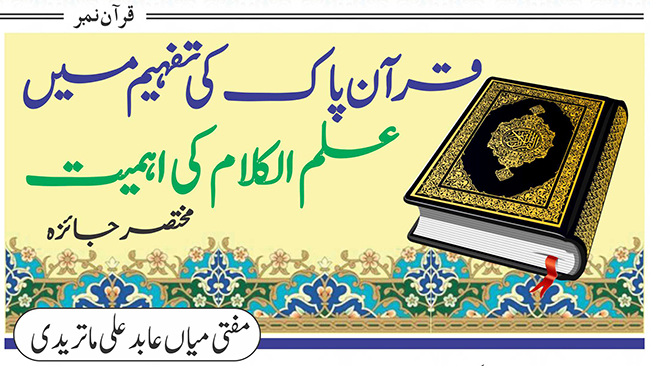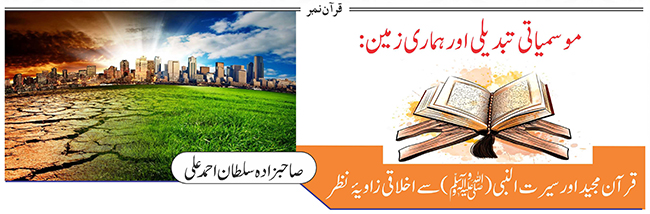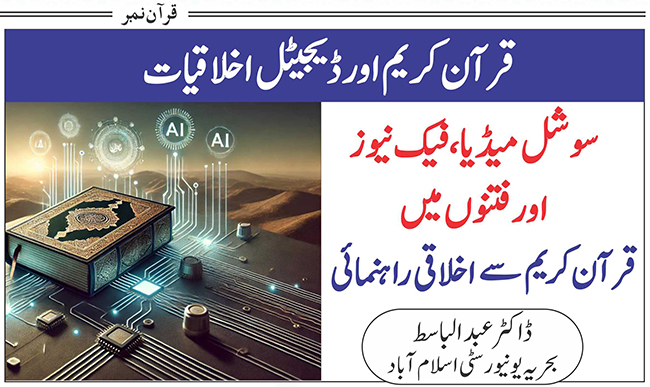|
اقبالؔ بھی ’اقبال‘ سے آگاہ نہیں ہے |
تاریخِ انسانی گواہ ہے کہ ہر قوم، ہر تہذیب، ہر عروج و زوال کے پیچھے ایک فکر، نظریہ اور تصورِ انسان کارفرما ہوتا ہے- کسی بھی معاشرے کی اصل قوت اس کی عسکری یا معاشی طاقت نہیں، بلکہ وہ فلسفیانہ فکر ہے جو اس کے شعور اور عمل کو سمت دیتی ہے-
فکر ایک بیج ہے جو کسی مفکر کے ذہن میں اُگتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ایک تہذیبی درخت میں بدل جاتا ہے- علامہ اقبالؒ اسی تسلسل کے ایک اہم سنگ میل ہیں،وہ مفکر جنہوں نے اسلامی فکر، مغربی فلسفے اور روحانی تجربے کو ایک ہم آہنگ کل میں ضم کرنے کی کوشش کی-
بانیٔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بجا طور پر کہا:
“If there were no Iqbal, there might not have been the idea of Pakistan”.
’’اگر اقبال نہ ہوتے تو پاکستان کا تصور شاید ہمارے ذہن میں بھی نہ ہوتا‘‘-
کیونکہ اقبال وہ مفکر تھے جن کے وجدان (intuition) میں سب سے پہلے ملتِ اسلامیہ کی خودی اور سیاسی خودآگاہی کی شعاع نمودار ہوئی-
اقبال کا تصورِ خودی دراصل وجودی سوال (existential questions) سے جنم لیتا ہے:
- میں کون ہوں؟
- میرا مقصدِ وجود کیا ہے؟
- کائنات میں میرا مقام کیا ہے؟
- کیا انسان بعض دیر مخلوقات کی طرح بے اختیار ہے یا خلیفۃُ اللہ فی الارض؟
یہ وہ سوالات ہیں جو سقراط (Socrates) کے ’’Know thyself‘‘ سے لے کر کانٹ (Kant) کے ’’What is man?‘‘ اور اقبال کے تصورِ ’’خودی ‘‘ تک ایک تسلسل میں نظر آتے ہیں-
اقبال کے نزدیک انسان محض حیوانِ ناطق (rational animal) نہیں، بلکہ ایک خلاق (creative) اور فعال روحانی مرکز ہے جو کائنات کے اندر خدا کی تخلیقی صفت سے متصف ہے- یہی تصور فلسفۂ خودی کا نچوڑ ہے-
|
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے |
اقبال کا فلسفہ نہ محض روحانیت یا مجرد عقل کا کھیل ہے، اور نہ ہی خالص فکری تجزیہ یا عقلیت پر مبنی ہے-بلکہ یہ ایک زندہ جدلیات (living dialectic) ہے جو انسان کی خودی کو مرکزِ فکر بناتا ہے-
اس فلسفے میں خودی صرف فرد کا شعور یا انا نہیں بلکہ ایک متحرک، تخلیقی اور ارتقائی قوت ہے جو انسان کو اپنی ذات، اخلاق اور تقدیر کے بارے میں غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے-اقبال کے نزدیک خودی کے ارتقاء میں عقل، وجدان، ارادہ اور عشقِ الٰہی سب شامل ہیں، اور یہ سب ایک مربوط عمل کی صورت اختیار کرتے ہیں-
اسی جدلی عمل کے ذریعے انسان:
- اپنی شناخت اور وقار کو پہچانتا ہے-
- اپنی فکری اور عملی صلاحیتوں کو بہتر اور بلند کرتا ہے-
- دنیا میں اپنی موجودگی اور اثر کو منفرد اور تخلیقی انداز میں ظاہر کرتا ہے-
اقبال غزالی سے روحانیت، ابن عربی سے منسوب وحدت الوجود کی لطافت، مولانا رومؒ سے عشق و حرکت اور کانٹ، نطشے، برگساں سے انسان کے عمل اور ارادے کی گہرائی حاصل کرتے ہیں- لیکن ان میں سے کسی سے استفادے پہ فخر نہیں کرتے بلکہ صدا کیلئے اپنے حلقوم کی تازگی قرآن مجید سے حاصل ہونے پہ فخر کرتے ہیں -
اقبال اور مغربی فلسفہ:
اقبال مغرب کے ناقد ضرور تھے، مگر معترض نہیں- وہ نطشے (Nietzsche) کے “Übermensch” کو انسانِ کامل کے قریب سمجھتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اقبال کا انسانِ کامل خدا سے منقطع نہیں بلکہ اس کا مظہر ہے-
نطشے کے نزدیک ’’خدا مر گیا ہے‘‘، مگر اقبال کے نزدیک انسان تبھی زندہ ہے جب اس کے اندر خدا کی صفتِ خلاقیت زندہ ہو-
اقبال نے برگساں (Bergson) کے ’’حیاتِ مسلسل‘‘ (elan vital) کو عشقِ الٰہی کے تصور سے ہم آہنگ کیا- ہیگل (Hegel) کی جدلیات (dialectics) کو انہوں نے قرآنی تصورِ ’’حرکت و ارتقاء‘‘ کی روشنی میں مطالعہ کرنے کی سعی کی اور کانٹ کی ’’حدودِ عقل‘‘ سے یہ نتیجہ نکالا کہ وجدان (intuition) اور روحانی تجربہ عقل سے بالا تر ایک حقیقت ہے-
اقبال اور اسلامی مفکرین:
اقبال کے فکری ارتقاء میں مجدد الف ثانی کی تجدیدی روح، امام غزالی کی ایمانی بصیرت، ابن عربی کی عرفانی گہرائی، فخر الدین عراقی کا عشق اور مولانا رومؒ کا حرکت و عمل کا فلسفہ، سب شامل ہیں-
اقبال نے ان تمام اثرات کو یکجا کر کے ایک ایسا نظامِ فکر تشکیل دیا جو اسلامی روحانیات اور جدید انسان کی عقلی تشنگی دونوں کو سیراب کرتا ہے-
|
سبَق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا |
یہ شعر دراصل اقبال کا اخلاقی مینی فیسٹو ہے،ایک ایسی امت کے لیے جو قیادت کے خواب دیکھتی ہے مگر کردار کی تطہیر بھول چکی ہے-
فلسفیانہ پہلو:
اگر نطشے کا سوال یہ تھا کہ انسان کو کس نے قید کیا؟تو اقبال کا جواب یہ تھا کہ انسان نے خود اپنی خودی کو بھلا کر خود کو قید کیا-اقبال کے نزدیک انسان کی اصل قید بیرونی نہیں بلکہ اندرونی غلامی ہے مثلاً غلامیِ فکر، غلامیِ خوف، غلامیِ تقلید-اسی لیے اقبال فرماتے ہیں:
|
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے |
اقبال کا فلسفہ انسان کی وجودی خودی اور معنوی آزادی (existential selfhood and spiritual freedom) کا تجزیہ ہے، جو اسلامی تناظر میں پیش کیا گیا ہے- یہ محض تصوف یا اخلاقی تعلیم نہیں، بلکہ ایک ایسا فکری نظام ہے جو انسان کی ذاتی شعور، ارادہ، اور تخلیقی قوت کو اس کی زندگی کے معنی تلاش کرنے کے مرکز میں رکھتا ہے-
اس نقطہ نظر سے اقبال کا فلسفہ انسان کو اپنی ذات کی پہچان، اپنی تقدیر کی ذمہ داری، اور کائنات میں اپنے کردار کی تخلیق کی دعوت دیتا ہے- یہ فلسفہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کا وجود محض وجودی واقعہ نہیں، بلکہ فعال، تخلیقی اور معنوی طور پر خود مختار ہے، جو اپنی زندگی کے مقصد اور سمت کا خود تعین کرتا ہے-
یوں کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کی فکر میں وجودیت (Existentialism) اور روحانیت (Spirituality) کا ایک مربوط امتزاج موجود ہے، جو فرد کو نہ صرف اپنی ذاتی شناخت کی تلاش میں رہنمائی دیتا ہے بلکہ اسے اخلاقی، فکری اور عملی ترقی کی طرف بھی مائل کرتا ہے-یہ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خدا کی تلاش میں کائنات کے راز کھولے، مگر خدا کے نمائندے کی حیثیت سے-
یہ فلسفہ اس انسان کا ہے جو عقل سے بھی آگے جاتا ہے، عشق سے بھی بلند ہوتا ہے، اور حرکت، ارادہ اور خودی کے ذریعے اپنے وجود کو معنی دیتا ہے-
اس لیے ڈاکٹر علی شریعتی کا کہنا بجا ہے کہ:
’’اقبال، اسلام کی چودہ صدیوں کا نچوڑ ہے‘‘-
بانیٔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اقبال کے لئے درست فرمایا:
“He will live as long as Islam will live.”
’’جب تک اسلام زندہ ہے، اقبال زندہ رہے گا‘‘-
یعنی اقبال زندہ ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہے اور اسلام زندہ ہے، کیونکہ انسان کے اندر خودی کی جستجو زندہ ہے-
٭٭٭