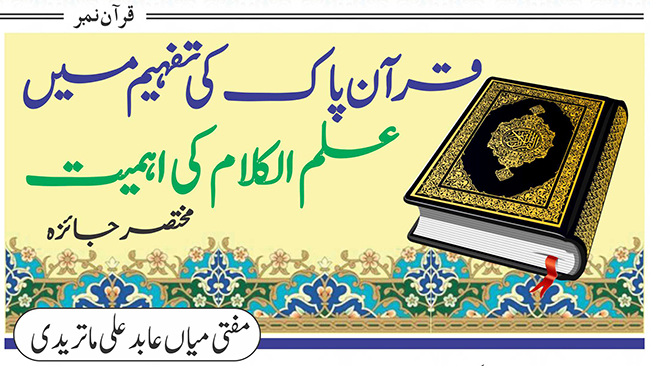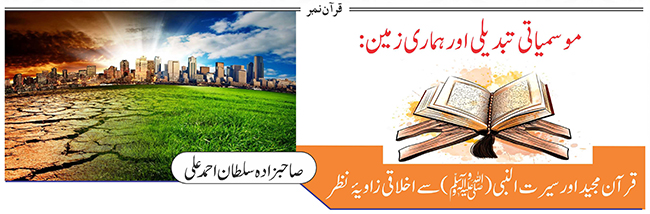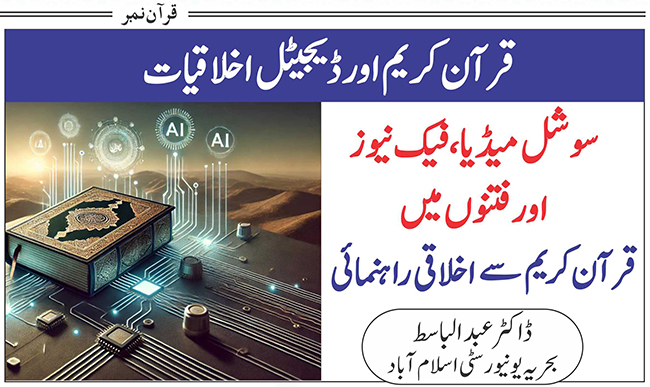ڈاکٹر کنیز یوسف، سابق وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی، نے ایک بار کہا تھا ؛ اور جنابِ جلیل عالی کے توسط سے یہ قول ہمیں منتقل ہوا کہ:
’’مدینہ منو رہ کے بعد اسلام کی سب سے بڑی کامیابی پاکستان ہے‘‘-
یہ جملہ، بظاہر سادہ ہے، لیکن غورکرنے پر پتہ چلتاہے کہ یہ حقیقت میں پاکستان کی تہذیبی بنیاد کے فلسفے کو مختصر ترین الفاظ میں بیان کرنے کا ایک سلیقہ ہے-جسے ہم مدینہ کہتے ہیں یہ پہلے یثرب تھا-یثرب سے مدینے تک کا سفرایک ایسی تہذیب کی 'ٹرانسفارمیشن' کا سفر ہے، جواپنی ثقافتی قوت کے عروج پرتھی جب اُسے یکایک تبدیل ہوجانا پڑا-یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا- گویاکوئی بہت بڑی متبادل ثقافتی قوت وارد ہورہی تھی جس نے سابقہ قوت کو شکست دی اور فقط 23 برس کے اندر اندرایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھ دی-یہ بہت بڑی متبادل ثقافتی قوت آخریکایک کیسے پیدا ہوگئی؟ بظاہراتنا بڑا ذہنی انقلاب جو پورے کے پورے سماج کویکسرنئے راستوں پر چلادے، کیونکر ممکن ہوا؟
اقبال کے نزدیک یہ رسالت مآب (ﷺ) کی اکمل ترین ہستی کےسراجِ مُنیرسے پھُوٹنے والا اُجالاتھا، جس نے نہ صرف وادیِ حجاز کے بیابانیوں کو’’خیابان و گلزاروباغ‘‘ میں بدل دیا بلکہ پوری انسانیت کو وجودی کرب کی عزلتوں سے نکال کر تکریمِ انسانیت سے روشناس کرادیا-انسانوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے گناہوں کی سزا کے طور پر اس تاریک دنیا میں موجود نہیں ہیں بلکہ انہیں یہاں بھیج کرموقع دیا گیا ہے-محض ایک مٹی کے پتلے کی سطح سے اُوپر اُٹھنے اور آگے بڑھ جانے کا موقع- دنیاتاریک ہے تو کیا ہوا، تم اِسے خود روشن کر سکتے ہو-یہ تمہارا قرارِ مکین اور مستقرِ اِلیٰ حین ہے-تمہیں یہاں رہ کر اپنی دنیا حَسِین بنانی ہے تاکہ تمہاری آخرت بھی حَسِین بن جائے-
یہ پیغام تھا ہی اتنا جاندار کہ وجودیت کے کرب میں مبتلا انسانیت کااحساسِ کمتری یکایک ختم ہونے لگا-اُداس انسانیت جیسے خوشی سے جھوم اُٹھی-دورِ قدیم سے فطرت کی سفاکیوں اور انسان کی کمتریوں، مجبوریوں اور معذوریوں کی جو دیومالائی داستانیں، مائیں اپنے بچوں کو سناتی آئی تھیں، وہ اب فطرت کو تسخیر کرتے ہوئے انسانوں کے کمالات کی داستانوں کے ساتھ بدلنا شروع ہوگئیں-
رسالت مآب (ﷺ) کی آمدکےساتھ شروع ہونے والا انقلابِ ذہنی ایک نئے انسان کی تعمیرکامنصوبہ تھا-ایک ایسا انسان جو ’’اپنی خودی پہچانتا‘‘ہے اوراس لیے مشکلاتِ حیات کو، اُس ذوق و تجسس اور قوت کے ساتھ کھیلنے کی چیزیں سمجھتاہے، جس ذوق وتجسس اورقوت کے ساتھ کوئی کھلاڑی اپنا من پسند کھیلتاہے-یہ واقعی ایک کلیتاً نیاانسان تھا-
چنانچہ یہ تھی وہ ٹرانسفارمیشن جس نے یثرب کو مدینہ ہی نہ بنادیاتھا بلکہ دنیائے قدیم اوردنیائے جدید کے درمیان ایک خطِ فاصل بھی کھینچ دیا تھا-یہ فقط ایک چھوٹے سے بنجر سماج کی زرخیزی کا مِشن نہیں تھا، بلکہ یہ پوری انسانیت کے ذہنی تناظر اورفلسفۂ حیات کومنقلب کردینے کا ایک جہانگیر منصوبہ تھا-
علامہ اقبال خطبات میں ایک جگہ اسی تناظر میں لکھتے ہیں کہ:
’’اس لحاظ سے دیکھاجائے تو یوں نظر آئےگا جیسے پیغمبراسلام (ﷺ) کی ذات گرامی کی حیثیت دنیائے قدیم اورجدید کے درمیان ایک واسطہ کی ہے- بہ اعتبار اپنے سرچشمۂ وحی کے آپ کا تعلق دنیائے قدیم سے ہے، لیکن بہ اعتبار اس کی روح کے دنیائے جدید سے- یہ آپ ہی کا وجود ہے کہ زندگی پر علم و حکمت کے وہ تازہ سرچشمے منکشف ہوئے جو اس کے آئندہ رخ کے عین مطابق تھے- لہذا اسلام کا ظہورجیسا کہ آگے چل کر خاطر خواہ طریق پر ثابت کردیاجائےگا، استقرائی عقل کا ظہور ہے‘‘-
لیکن سوال یہ ہے کہ وہ فلسفۂ حیات کیا تھا، جس نے اقبال کے بقول دنیائے جدید کی بنیادرکھی اورزندگی پر علم و حکمت کے وہ تازہ سرچشمے منکشف کیے جو اس کے آئندہ رخ کے عین مطابق تھے؟
اس سوال کا جواب اگرچہ رسالت مآب (ﷺ)کی حیاتِ طیبہ اور قرانِ حکیم کی ایک ایک سطر سے عیاں ہے، تاہم جس روزقرانِ حکیم کی آیت،’’ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا‘‘[1]کے ذریعےدینِ اسلام کے مکمل ہوجانے کا اعلان نشرکیاگیا، اُسی روز رسالت مآب (ﷺ) نے اِس فلسفۂ حیات کاسب سے بڑا بنیادی اصول بھی بیان فرمایا-جب فرمایا:
’’یَا اَیُّھَا النَّاسُ ! اَلَا اِنَّ رَبَّکُمْ وَاحِدٌ وَاِنَّ اَ بَاکُمْ وَاحِدٌ‘ اَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِیٍّ عَلٰی اَعْجَمِیِّ وَلَا لِعَجَمِیٍّ عَلٰی عَرَبِیٍّ وَلَا لِاَحْمَرَ عَلٰی اَسْوَدَ وَلَا اَسْوَدَ عَلٰی اَحْمَرَ اِلاَّ بِالتَّقْوٰی‘‘
’’اے لوگو ! آگاہ ہو جاؤ ‘ یقینا تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے- خبردار ! نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر- اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر- فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے‘‘-
آپ(ﷺ) نے گویا پوسٹ ماڈرنزم کی ایجاد سے 1400 برس قبل ہی بائنری متضادات (Binary Oppositions) کے خاتمےکوبنیادی فلسفۂ انسانیت قراردےدیا- تکمیلِ دینِ اسلام کے روز، خطبہ حجۃ الوداع کے دوران اس اعلان کا ہونا اپنے اندر بہت گہرے معانی رکھتاہے-
چنانچہ جب علامہ اقبال رسالت مآب (ﷺ) کی ذاتِ اقدس کو دنیائے قدیم اور دنیائے جدید کے درمیان واحد واسطہ قراردیتے ہیں، تو ایک لحاظ سے وہ دنیائے قدیم کو دنیائے جدید سے الگ بھی کردیتے ہیں-اورمزید یہ کہہ کر ’’اسلام کا ظہور استقرائی عقل کا ظہور ہے‘‘، گویا وہ میکانزم بھی بتادیتے ہیں جس کی بدولت عالمِ انسانیت کی، دنیائے قدیم سے دنیائے جدید میں 'ٹرانسفارمیشن' ہوئی-استقرائی عقل کہتے ہیں اس عقل کو جو کُلیات کے علم کی بجائے جزیات کے علم پرتوجہ مرکوز کرتی ہے-رسالت مآب (ﷺ) کی بعثت سے قبل دنیائے قدیم کا انسان کلیات کے علم کو ہی علم سمجھتا تھا اورجزیات کے علم کو ناپسند کرتاتھا-اقبال کے الفاظ میں:
’’سقراط کی توجہ صرف عالمِ انسانی پر تھی-اس کے نزدیک انسان کے مطالعے کا بہترین موضوع انسان ہی ہوسکتاہے، نہ کہ نباتات اور حشرات، یا ستاروں کی دنیا- مگر اس سے کس قدر مختلف ہیں قرانِ پاک کی تعلیمات، جس کا ارشاد ہے کہ شہد کی مکھی ایسی حقیر شے بھی وحی الٰہی سے بہرہ ور ہوئی اور جس نے بار بار اس امر کی دعوت دی کہ ہواؤں کے مسلسل تغیر و تبدل کا مشاہدہ کیاجائے، نیز دن رات کے اختلاف، تاروں بھرے آسمان اور بادلوں کا جو فضائے لامحدود میں تیرتے پھرتے ہیں-سقراط کے شاگردِ رشید افلاطون کو بھی ادراک بالحواس سے نفرت ہی رہی- اس کا خیال تھا ادراک بالحواس سے کوئی حقیقی علم تو حاصل نہیں ہوتا ہم اس کی بنا پر صرف ایک رائے قائم کرسکتے ہیں- برعکس اس کے قرانِ مجید نے سمع و بصر کا شمار اللہ تعالیٰ کے گراں قدر انعامات میں کیا اور عندللہ اپنے اعمال و افعال کا جواب دہ ٹھہرایا-‘‘
استقرائی علم جزیات کا علم تھا جولازمی طورپرانسانیت کو بالآخر سائنسی علوم کی طرف متوجہ کرنے والا تھا-اقبال خطبات میں لکھتے ہیں کہ یورپ کے بعض مؤرخین کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ آخراسلام کا ظہورجزیرۂ عرب میں کیوں کر ہوا؟ ان کے خیال میں اتنے بڑے مذہب کا ظہور قدرتی طورپر تو روم یا فارس میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس وقت کی عظیم تہذیبیں تھیں اوران کے لوگوں کو ضرورت تھی، ایک نئے مذہب کی، نہ کہ دنیا سے کٹے ہوئے ایک دوردراز کے جزیرہ نما، یعنی حجاز کواس کی ضرورت تھی-اقبال جواب میں کہتے ہیں کہ ’’عالم فطرت اپنی ضروریات کا مشاہدہ کر لیتا ہے‘‘- عالمِ فطرت نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فارس و روم (اور مشرق و مغرب) تک روشنی پہنچانے کا اہتمام بھی عرب میں ہی کیا جا سکتا تھا-لیکن اگر ہم اُس میکانزم پر غور کریں جس کی بدولت عرب کی اِس روشنی نے دنیائے قدیم کو دنیائے جدید میں بدلا، توٹھیک ٹھیک نظر آجاتاہے کہ عرب سے یورپ تک یہ فلسفۂ حیات کن مراحل سے گزرکر منتقل ہوا-
روشنی کا سفر، صحرائے عرب سے جدید یورپ تک:
جزیرۂ عرب کا زیادہ حصہ ایک تپتا صحرا ہے-یہاں زرخیز زمینیں کبھی بھی نہیں رہیں-اس لیے صدیوں تک یہاں کے لوگوں کا ذریعۂ معاش صرف تجارت ہی تھا- قرونِ وسطیٰ میں عربوں کے تجارتی روابط رومیوں، ایرانیوں اور یہودیوں کے ساتھ تھے- عرب کے لوگ چونکہ سوداگر تھے اس لیے ملک ملک گھومتے تھے-
کارل مارکس کی تاریخی مادیت سے تہذیب کا جو تصور ابھرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تہذیب کسی قوم کے اقتصادی حالات میں تغیرکے تاریخی تجربے کی عکاس ہوتی ہے-یعنی کسی قوم کی معیشت میں جوجوتغیرات برپاہوتے ہیں وہ اس قوم کی سماجی اقدار کو وضع کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں- یہی اقتصادی تغیرات ہی کسی قوم کا حقیقی تاریخی تجربہ ہوتے ہیں-اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو قبل از اسلام کا حجاز ایک تاجر اور کاروباری حجاز تھا- جبکہ اسی زمانے کا یورپ کاروباری یورپ نہیں تھا-
یہ ایک مشاہدے میں آنے والی حقیقت ہے کہ اگر کسی قوم کا ذریعۂ معاش اُسے گھر پرہی یعنی اپنے وطن میں ہی دستیاب ہو تو بیرونی اقوام کے ساتھ اس کا تعامل محدود ہوتا ہے-نتیجتاً بیرونی اقوام کی ثقافت، ان کے رسم و رواج، علم و ایجاد اورزبان و ادب تک بھی اس کی رسائی ویسے نہیں ہوپاتی، جیسے کسی سوداگرقوم کے افراد کی ہوسکتی ہے-اس کے برعکس اگر کسی قوم کے ذریعۂ معاش کا تعلق ہی بیرونی اقوام سے تعامل کے ساتھ ہو، یعنی وہ قوم کاروباری ہو، تولازم ہوجاتاہے کہ اس قوم میں ’’قبولیت کی لچک‘‘ بھی پائی جائے-قبولیت کی لچک سے مراد ہے، بیرونی اقوام کے رسم و رواج، علم و ایجاد اورزبان و ادب کو ناپسندیدگی سے نہ دیکھنے کی وسعتِ نظری و قلبی-دراصل وہ خطۂ زمین جو ذرخیز ہے اور جہاں کے باشندوں کوخوارک، کھیتوں اورفصلوں سے مل جاتی ہے وہاں لوگوں کو اپنے علاقے سے باہر جانے کے مواقع بہت کم میسر آتے ہیں-اس لیے اُن میں قدرتی طور پر حفظِ خویش (قبیلہ، ثقافت،علاقہ) کانظام بھی مضبوط ہوتاہے،اور نئے خیالات، نئی رسموں اور علم و ایجاد کے خلاف ان کا مدافعتی نظام بھی خاصامضبوط ہوتاہے-
اس کے برعکس جن خطوں میں زراعت نہیں ہوتی یعنی وہ فصلوں اور کھیتوں سے اپنی خوراک حاصل نہیں کرپاتے، انہیں مجبوراً تجارت اختیار کرنا پڑتی ہے- ایسے کاروباری یا تاجر معاشروں میں لوگوں کو اپنے علاقوں سے باہر جانے کے متعدد اور مسلسل مواقع میسر آتے رہتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ نت نئی سوچوں کا ادغام، نئے نئے خیالات اور رسم رواج کی درآمد کی صورت ظاہر ہوتاہے- چنانچہ ایسے معاشرے قدرتی طور پر جدید معاشرے ہوتے ہیں-
زمانہ ٔ قبل ازاسلام کا عرب معاشرہ ایک ایسا ہی معاشرہ تھا-قران کریم کی سُورۂ قریش میں قریش کے تجارتی قافلوں کا ذکرکرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ’’رِحْلَۃَ الشِّتَآءِ وَ الصَّیْفِ‘‘[2] قریش سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر کر کر کے اب ان سفروں سے مانوس ہوچکے ہیں-یعنی انہیں تجارتی اسفارکی عادت ہوچکی ہے-یہ گویا خود اللہ تعالیٰ قریش کے مرچنٹ کیپٹالزم کا تذکرہ فرماتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ تجارت کے لیے سفر کرنا قریش کا کلچرہے-
عرب جس قسم کی اقتصادیات کے حامل تھے، مارکس کے الفاظ میں ہم اسے مرچنٹ کیپٹالسٹ سوسائٹی کہیں گے-مرچنٹ کیپٹالسٹ وہ معاشرہ ہوتا ہے جہاں سے تاجر دوردراز کے علاقوں میں اپنی اشیائے فروخت لے کر جاتے ہیں اور دوردراز کے علاقوں سے اپنے وطن میں اشیائے فروخت لے کر آتے ہیں- بالکل ویسے جیسے قریش کیا کرتے تھے-مارکس نے داس کیپٹال کے والیم تھری میں وینس اور جنووا کے معاشروں کو مرچنٹ کیپٹالسٹ معاشروں کی بہترین مثالوں کے طورپر پیش کیا ہے اور اُنہیں قرونِ وسطیٰ میں (اُس وقت کے)مستقبل کے انڈسٹریل کیپٹالزم کے شاخسانے قراردیا ہے-جبکہ وینس اورجنووا اُن شہروں میں شامل ہے جہاں اس دور کے عرب تاجروں کی مستقل آمدورفت جاری رہتی تھی-
تاریخ میں اس بات کے بے پناہ شواہد موجود ہیں کہ یہ اسلامی مرچنٹ کیپٹالزم ہی تھا جس کاتحفۂ جدیدیت اُنیسویں صدی کے یورپ میں ،ماڈرنٹی کی صورت ظاہرہوا-عربوں کا تاجر ہونا کس کس طرح سےاپنے وقت میں یورپ کی نشاۃِ ثانیہ (renaissance) کا باعث بنا، تاریخ کے اس باب کا مطالعہ نہایت درجہ اہم ہے-چودھویں صدی عیسوی کے اطالوی شاعر پیٹرارک کی ادبی تحریریں اور اس کی سوانح پڑھیں تو اندازہ ہوجاتاہے کہ عباسی خلافت کے آخری دنوں میں کس طرح یورپ میں کلاسیکی لٹریچرکو عربی سے لاطینی میں ترجمہ کرنے کی تحریکیں اُٹھ رہی تھیں-پیٹرارک نشاۃِ ثانیہ کے ان اوّلین ادیبوں میں شامل ہے جنہوں نے قدیم یورپ کی شان و شوکت کو دوبارہ آواز دی اور نشاۃِ ثانیہ کی بنیاد ڈالی- پیٹرارک کا مؤقف تھا کہ عربی علم و ادب اوّل دور کے یونانی(یعنی یورپی) علم و ادب کا ہی ترجمہ ہے، اور اِس لیے اپنا کھویا ہوا اثاثہ عربی سے واپس لاطینی میں ترجمہ کیا جانا چاہیے، تاکہ یورپ کے علوم یورپ کو واپس میسر آئیں-چنانچہ یہ عربی سے لاطینی میں ہونے والے تراجم ہی تھے جو یورپ کی نشاۃِ ثانیہ کا باعث بنے-عربی سے لاطینی تراجم کی صدی گیارھویں اوربارھویں صدی عیسوی ہے، جبکہ یورپ کی نشاۃِ ثانیہ کی صدی تیرھویں اور چودھویں صدی عیسوی ہیں-
تاریخِ یورپ میں نشاۃِ ثانیہ کا پورا دور مسلمانوں سے مرعوبیت کا دور بھی ہے-ڈاکٹرغلام جیلانی برق نے اپنی کتاب ’’یورپ پر اسلام کے احسانات میں‘‘ ولیم ڈریپر کے حوالے سے لکھاہے کہ قرونِ وسطیٰ کے یورپی، اسلامی تہذیب کی نقل کیا کرتے تھے-جب چرچ نے فرانس کے بادشاہ فلپ کو سزا سنائی تھی تو فہرستِ الزامات میں یہ بھی درج تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرح روزانہ ہاتھ منہ دھوتاہے-ڈاکٹر برق لکھتے ہیں کہ یورپی ممالک کے بادشاہ اپنی قباؤں پر عربی کی تحریریں لکھوایا کرتے تھے تاکہ وہ ماڈرن نظرآئیں اورلوگوں پر ان کا رُعب پڑے-
نشاۃ ثانیہ کے ہی زمانے میں اہلِ یورپ میں شوقِ سیاحت نے رواج پانا شروع کیا-اہل یورپ کی انہی ابتدائی سیاحتوں نے اپنے زمانے کے فیوڈل یورپ کو کاروباری یورپ میں ڈھالنے کی بنیاد ڈالی- یہ وہی زمانہ ہے جب مارکوپولو مشرقی ممالک کی سیاحت کے لیے نکلا - نئی نئی دنیاؤں کی معلومات یورپ آنا شروع ہوئیں اور ایک ہزار برس سے بدترین فیوڈلزم میں جکڑا ہوا پورا مغربی یورپ پہلی بار تجارت کے راستے پر چل پڑا-
پھر نشاۃ ثانیہ کے نتیجے میں یورپ میں تحریکِ اصلاح (reformation) شروع ہوگئی-ریفارمیشن سے مراد ہے مذہبی عقائد میں اجتہاد - مسیحی عقائد کی ریفارمیشن میں سب سے بڑا نام مارٹن لوتھر کاہے-مارٹن لوتھر کی تحریکِ اصلاح کو کیتھولک چرچ نے مستردکردیا تو یہ تحریک ایک نئے فرقے میں ڈھل گئی، جسے پروٹیسٹنٹ کہاجاتاہے-اوریہ پندھرویں صدی کی بات ہے-اسی صدی میں واسکوڈے گاما نے ہندوستان دریافت کیا -
ریفارمیشن کا ایک لازمی نتیجہ عقلی اورظاہری علوم کی طرف مائل ہونے کی صورت میں نکلنا تھا- اوریوں یورپ میں روشن خیالی(Enlightenment) کا دورشروع ہوا- عام طورپر یہ سمجھاجاتاہے کہ فقط یورپ کے عہدِ روشن خیالی کی وجہ سے یورپ میں سائنس نے جنم لیا- راجربیکن کو بابائے تجربی منہاج(Father of scientific method) کہا جاتا ہے-یعنی یہ کہاجاتاہے کہ یورپ میں استقرائی عقل کا آغازراجر بیکن نے کیا-اس میں شک نہیں کہ راجر بیکن کا تجربی منہاج ایک فلسفیانہ انقلاب تھا جس نے یورپ کی قرونِ وسطیٰ کی جامد علمی روایت کو توڑا اور تجربہ و مشاہدہ کو علم کی روشنی کا مرکز بنادیا-آگے چل کر جب فرانسس بیکن، گیلیلیو اورنیوٹن نے راجربیکن کے تجربی منہاج کے اصولوں پر مظاہر فطرت کا مطالعہ شروع کیا تو گویا عظیم سائنسی انقلاب کے دروازے چوپٹ کھل گئے-لیکن اقبال اپنے خطبات میں جب یہاں پہنچتے ہیں تو پھر ایک سوال اُٹھاتے ہیں- لکھتے ہیں:
’’سوال یہ ہےکہ راجر بیکن نے علم و حکمت کا درس لیا تو کہاں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے اور یہ کہ اندلس کی اسلامی درس گاہوں میں- چنانچہ اس کی تصنیف ’اوپس ماژس‘ کے باب پنجم کا مطالعہ کیجیے جس کا تعلق مرایا سے ہے تو صاف نظر آجائے گا کہ یہ ابن الہیثم ہی کی بصریات کا چربہ ہے-پھر اس تصنیف پر ابن حزم کے اثرات بھی نمایاں ہیں- یورپ نے اس حقیقت کو اگرچہ بہت دیر میں تسلیم کیا کہ سائنس کا منہاج دراصل مسلمانوں کی دریافت ہے لیکن بالآخر اسے اس کا اعتراف کرنا ہی پڑا ‘‘-
اس کے بعد اقبال اپنے اِس دعوے کی دلیل میں کہ ’’یورپ کو بالآخر مسلمانوں کی دریافت کا اعتراف کرنا پڑا‘‘ رابرٹ بری فولٹ کی کتاب ’’تشکیل انسانیت‘‘ سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں:
’’یہ آکسفورڈ اسکول میں ان کے جانشین تھے جن سے راجر بیکن نے عربی اور علومِ عربیہ کی تعلیم پائی- لہٰذا تجربی منہاج کی اشاعت پر فخر کرنے کا حق راجر بیکن کو پہنچتاہے، نہ اس کے مشہور ہم نام کو- راجر بیکن کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ مسیحی یورپ میں اس کا شمار اسلامی سائنس اور منہاج سائنس کے مبلغین میں ہوتا ہے- وہ یہ کہتے کبھی نہیں تھکا کہ اگر اس کے معاصرین کو سچ مچ علم کی تلاش ہے تو انہیں چاہیےعربی زبان اور عربی علوم کی تحصیل کریں-رہی یہ بحث کہ منہاجِ تجربی کس کی ایجاد ہے- سویہ بھی ایک نمونہ ہےان زبردست غلط بیانیوں کا جو مغربی تہذیب کے مبدأ و ماخذ کے بارے میں کی جاتی ہیں- اس لیے کہ بیکن کا زمانہ آیا تو عربوں کا تجربی منہاج سارے یورپ میں پھیل چکا تھا اور لوگ بڑے اشتیاق سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے‘‘-
چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یورپ کا علمی عروج عربوں کی استقرائی عقل کا ہی تحفہ ہے جو جدیدیت کی صورت، کم سے کم چار صدیوں میں، یورپ منتقل ہوا اور یورپ کی ٹرانسفارمیشن کا سبب بنا-اقبال نے خطبات میں لکھا ہے کہ ، ’’ اگر ہمارا نوجوان ذہن آج مغربی تہذیب کی طرف مائل ہونا چاہتاہے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ مغربی تہذیب اسلامی تہذیب کے ہی بعض پہلوؤں کا عکس ہے‘‘-
ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیبی ساخت:
پندرھویں صدی عیسوی کے وسط میں، جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا، تو ایشیا اور یورپ کے درمیان قدیم تجارتی راستے عثمانی ترکوں کے زیرِ نگین آ گئے- اس کے بعد یورپی طاقتوں کو مشرق، بالخصوص ہندوستان، تک پہنچنے کے لیے نئے بحری راستے تلاش کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی- چنانچہ واسکو ڈے گاما، پرتگالی بادشاہ کی سرپرستی میں، 20 مئی 1498ء کو جنوبی ہندوستان کے ساحلی شہر کالی کٹ (موجودہ کوژیکوڈ، کیرالہ) پہنچا-
اس وقت شمالی ہند میں سلطان سکندر لودھی دہلی کی سلطنت کا حکمران تھا، تاہم واسکو ڈے گاما کی ملاقات کسی مسلم سلطان سے نہ ہو سکی- وہ صرف زمورین حکمران (کالی کٹ کا مقامی ہندو راجا) سے ملا اور چند تجارتی اشیاء لے کر جلد ہی پرتگال واپس روانہ ہو گیا تاکہ اپنے بادشاہ کو یہ خبر دے سکے کہ ہندوستان تک سمندری راستہ دریافت ہو چکا ہے اور یہ ملک دولت، مصالحہ جات اور تجارتی امکانات سے مالا مال ہے-
یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان تاجر جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں، بالخصوص کالی کٹ کی بندرگاہوں پر تجارت، اثر و رسوخ اور سفارتی حکمت عملی کے اعتبار سے نہایت فعال اور بااثر تھے- تاریخی روایت ہے کہ جب واسکو ڈے گاما 1498ء میں کالی کٹ کے زمورین (مقامی ہندو راجا) سے ملاقات کے لیے پہنچا، تو دربار میں کچھ مسلمان، خصوصاً عرب تاجر پہلے سے موجود تھے- ان تاجروں نے نہ صرف زمورین کے ساتھ دیرینہ اعتماد کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے پرتگالیوں کے بارے میں راجا کو چونکادینے والی سیاسی بصیرت بھی دی-
ممتاز ہندوستانی مؤرخ کے ایم پنی کّر (K.M. Panikkar) لکھتے ہیں:
’’عرب تاجروں نے زمورین کو خبردار کیا کہ پرتگالی محض تاجر نہیں، بلکہ سلطنتوں کو زیر کرنے والے لوگ ہیں- ان کی یہ رائے واسکو ڈے گاما کی سرد مہری سے بھرپور پذیرائی کا سبب بنی‘‘-
اسی سبب راجہ زمورین نے واسکو ڈے گاما کی پیش کردہ معمولی اور غیر متاثرکُن اشیاء کو سرد مہری سے دیکھا اور نہ کوئی تجارتی وعدہ کیا، نہ کوئی سیاسی التفات دکھایا- واسکوڈے گاما کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ صرف ایک بندرگاہ تک نہیں، بلکہ ایک صدیوں پر محیط تجارتی روایت اور ایک ایسے مستحکم اقتصادی توازن سے ٹکرا گیا ہے، جس کے محور میں عرب تاجروں کی غیر معمولی بصیرت اور رسوخ موجود تھا-
اُس دور میں ہندوستانی مسلمان، عرب تاجروں کی رہنمائی اور تقلید کے زیرِ اثر، تجارت کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہو چکے تھے- بلکہ کئی مواقع پر عربوں سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے، اس لیے کہ اُن کا کردار صرف تاجر کا نہ تھا بلکہ وہ صنعت کاری میں بھی پیش پیش تھے- ہندوستانی مسلمان وہ طبقہ تھے جنہوں نے یورپ سے کہیں پہلے مرچنٹ کیپٹلزم سے انڈسٹریل کیپٹلزم کی طرف پیش قدمی کی تھی اور جدیدیت کی شروعات کو محسوس کر لیا تھا-وہ معاشی ثمرات، وہ تجارتی اُفق اور وہ سیاحتی تجربات جنہیں اہلِ یورپ نے پندرھویں اور سولہویں صدی میں دریافت کرنا شروع کیا، ہندوستانی مسلمان انہیں آٹھویں سے سولہویں صدی عیسوی تک اپنی آنکھوں سے دیکھ اور برت بھی چکے تھے-
اسلام کا ورودِ ہند بھی ان ہی عرب تاجروں اور ان کے ساتھ آنے والے صوفیائے کرام کے ذریعے ہوا، جن کی علمی روشنی، روحانی خوشبواور اقتصادی فہم نے برصغیر کی زمین کو بدل کر رکھ دیا- ہندوستانی مسلمانوں نے تجارت عربوں سے سیکھی اور ایسی محنت و حکمت سے سیکھی کہ چند ہی صدیوں میں ہندوستان کو اہلِ یورپ کے لیے سونے کی چڑیا بنا ڈالا-چنانچہ جب یورپی اقوام نے برصغیر کا رُخ کیا، تو درحقیقت ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیبی تابناکی، اقتصادی خوشحالی اور صنعت کاری کی چمک ہی اُنہیں کھینچ کر یہاں لائی تھی-یہ وہ عہد تھا جب بحیثیت مسلمان، ہندوستانی مسلمانوں کی اقتصادی فعّالیت دنیا میں ایک نظیر بن چکی تھی اور بحیثیت تہذیبی وحدت، وہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک زندہ اور بامعنی پُل کی حیثیت اختیار کرچکے تھے-
ہندوستانی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں پہلا بڑا تہذیبی اور فکری انحراف اُس وقت ظہور پذیر ہوا جب مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اپنے سیاسی افکار کی بنیاد قدیم ہندو فلسفی شنکراچاریہ کے نظریۂ سِریت پر رکھی، اور اسے دینِ الٰہی کے نام سے موسوم کیا- اکبر کی خواہش تھی کہ اُس کی سلطنت کی رعایا مذہبی تفرقوں سے بالا ہو کر ایک ہم آہنگ وحدت میں ڈھل جائے- ہندوستان کئی مذہبی اور لسانی گروہوں کا مجموعہ تھا-اکبرنے شنکریّت کے ذریعے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم بنانا چاہا- وہ نہیں جانتاتھا کہ فکرِ قرانی اس طرح کے تصورِ حلول و ادغام کی اجازت نہیں دیتی-
اقبال کا سب سے زوردار پیغام:
اقبال نے اسرارِخودی میں جس وجدانی جوش کے ساتھ اس نکتے کی صراحت کی ہے، تاریخ علم میں اس کی مثال نہیں ملتی-اقبال نے شنکری نکتہ نظر کوفرد کی خودی کا قاتل اور سماج کی روحانی موت کا ذمہ دارٹھہرایا ہے-بعض ناقدین اس مفہوم کی بات لکھتے ہیں کہ ہر مستبد حکمران کے لیے اس طرح کے نظریات پرکشش ہوتے ہیں کیونکہ یہ نظریہ انسانوں کو بظاہر محبت اور ہم آہنگی کا درس دیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ محبت مرکز میں بیٹھے بادشاہ کی محبت میں ڈھل جاتی ہے اور یوں حکمران کی سیاسی مرکزیت کو الٰہیاتی جواز مل جاتا ہے-
اقبال کی نظر میں وہ تمام فکری یا روحانی نظریات، جو فرد کی خودی کو مٹانے کی تلقین کرتے ہیں، اسلامی روح کے خلاف ہیں- خصوصاً وہ تعبیرات جو فرد سے قوتِ عمل، ارادے کی شدت اور مزاحمت کی جرات چھین لیں جیسے ملوکیّت، تھیوکریسی یا رہبانی تصوف ، اقبال کے ہاں شدید تنقید کا نشانہ بنتی ہیں-
؎ اے کُشتہءِ سلطانی و مُلّائی و پیری
اسرارِ خودی کی پانچویں نظم میں اقبال ایک تمثیل کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ کس طرح کمزور، خوف زدہ اور مصلحت کوش قومیں اپنی بے عملی کو ’’روحانیت‘‘ کا نام دے کر خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہیں-اقبال کی تمثیل میں ایک گوسفند خود کو صاحبِ الہام صوفی ظاہر کرتا ہے اورجنگل کے جانوروں بشمول شیرچیتا، سب کو، نرمی، عجز اور ترکِ خودی کا وعظ دینے لگتا ہے-
|
صاحب آوازۂ الہام گشت |
’’وہ (گوسفند) الہام کا دعوے دار بن بیٹھااور خون آشام شیروں کا واعظ بن گیا-یہ واعظ اس سبق پر زور دیتا ہے کہ‘‘:
|
ہر کہ باشد تند و زور آور شقی است |
’’جو بھی تیز خو اور طاقتور ہو، وہ بدبخت ہے- زندگی کااستحکام تو خودی کو مٹا دینے میں ہے-یعنی زور، حرکت اور خودی کو شر اور شقاوت کہا جا رہا ہے- اسی میں اقبال اس مذہبی رجحان پر بھی تنقید کرتے ہیں جو فقر، قناعت اور ترکِ دنیا کو عین نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے‘‘-
|
روح نیکان از علف یابد غذا |
’’نیک لوگوں کی روح گھاس سے غذا پاتی ہے اور جو گوشت نہیں کھاتا، وہی خدا کا پسندیدہ ہے-سب سے سنگین بات تب ہوتی ہے جب اسی سوچ کے تحت استبداد اور ظلم کے سامنے سرتسلیم خم کر دینے کو ’روحانی بلندی‘ سمجھا جاتا ہے‘‘-
|
میش نتواند بزور از شیر رست |
’’گوسفند طاقت کے زور سے شیر سے نجات نہیں پا سکتی- وہ کہتی ہے، ہمارا بازو چاندی سا نرم ہےاور شیر کا بازو فولاد کی طرح سخت‘‘-
اکبری نظریہ تصوف کا رد عمل سخت گیر ملائیت کی صورت میں متوقع تھا ، اقبال نے شنکری رجحان کے رہبانی تصوف کے ساتھ ساتھ ملائیت کا بھی رد کیا اور تاریخی مصرعہ کہا :
؎دینِ ملا فی سبیل اللہ فساد
اقبال کے نزدیک بے عمل تصوف کا نظریہ یعنی نفی خودی، اگر کسی سماج کا اجتماعی عقیدہ بن جائے تو اس کے گہرے معاشرتی نتائج مرتب ہوتے ہیں- ایسا معاشرہ دھیرے دھیرے زندگی کی ضرورتوں کو محدود کرنے لگتا ہے- خاندانی نظام متاثر ہوتاہے اور گھراورخاندان روحانیت کے راستے کی رکاوٹیں محسوس ہونے لگتے ہیں-
اِسی طرح اقتدار پسند ملائیت بھی معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے ، جیسے یزید کے درباری علماء نے کربلا کے واقعے سے چشم پوشی کرنے کیلئے جامد تقدیر پرستی کو فروغ دیا -
حیران کن امر یہ ہے اکبر نے جس شعبہء دین (یعنی تصوف) کا سہارا لے کر ایک بدعت کا آغاز کیا اس کے خلاف سب سے بڑی مزاحمت ملائیت سے نہیں بلکہ خود اپنے عہد کے امامِ تصوف مجدد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندیؒ نے بپا کی –
اکبری خطرے کو بھانپ کر مجدد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندیؒ تاریخ کے اُفق پر نمودار ہوئےاور شنکراچاریہ کے فلسفۂ حلول کے اس خاموش مگر گہرے حملے کے سامنے عقیدۂ توحید کا استوار قلعہ تعمیر کیا-جہانگیر کے دور میں بھی یہ باطنی مداخلت جاری رہی-اگر اُس وقت حضرت مجددؒ فکری میدان میں نہ نکلتے تو نہ صرف اسلامی ملی تشخص مٹ جاتا، بلکہ بعد کی صدیوں میں پاکستان جیسی کسی ریاست کا تصور بھی محال ہوتا- اسی بصیرت و احسان کے اعتراف میں علامہ اقبالؒ نے حضرت مجدد کے مزار پر کھڑے ہو کر یہ بلیغ اور تاریخ ساز اشعارکہے تھے-
|
گردن نہ جھُکی جس کی جہانگیر کے آگے |
ہندوستان میں مسلمانوں کا تہذیبی انحطاط:
مجددالف ثانی کی بروقت مداخلت سے اکبر کا دینِ الٰہی، اکبر کے بیٹے جہانگیر کے زمانے کو بھی عبور نہ کرپایا-یہ چونکہ زیادہ طویل عرصہ نہیں تھا اس لیے مسلم سپرٹ پر اکبر کا یہ حملہ ہندوستانی مسلمانوں کی مجموعی فطرت پر کوئی قابلِ ذکر اثرات نہ ڈال سکا-وہ جیسے جوشیلے، فعال اورتجارت پسند پہلے تھے، ویسے ہی رہے-چنانچہ اورنگ زیب عالمگیر کے زمانے تک تجارت اورصنعت کاری ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی شناخت تھی-لاہورپوری دنیا میں سُوتی کپڑے کا سب سے بڑا مرکز تھا- انگریز کی آمد سے پہلے لاہور میں کپڑے کےتاجروں کی شان و شوکت قابلِ دید ہواکرتی تھی-اپنی دولت کی نمائش کے لیے وہ سولہ گزلمبی، سفید سُوتی کپڑے کی پگڑی باندھا کرتے تھے-برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز تاجر لاہورکے دکانداروں سے ہمیشہ مرعوب تھے-اُس عہد کے ہندوستانی مسلمانوں کی اقتصادی کامیابیوں کی تفصیل سید محمد طفیل منگلوری علیگ کی کتاب ’مسلمانوں کا روشن مستقبل‘ میں دیکھی جاسکتی ہے-
چنانچہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے اولین زمانے تک ہندوستانی مسلمان ایک طاقتور، پڑھی لکھی اورفعّال قوم تھے-وہ مہذب تھے،صاف ستھرے لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے، تقریبات میں جمع ہوتے اورضیافتوں میں شاہ خرچیاں کرتے تھے-سیّد طفیل علیگ کے مطابق مسلمان حکمرانوں کے ایوانوں میں انگریزتاجروں کی آمدورفت سےہندوستانی مسلمان حکمرانوں کے طور اطواربھی بدلناشروع ہوگئے تھے-
برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جہانگیر کے عہد میں، سورت میں اپنا پہلا تجارتی مرکز قائم کرنے میں کامیاب ہوچکی تھی- اورنگزیب عالمگیر کے ابتدائی دور تک کمپنی محض ایک باادب تجارتی ادارہ تھی، جو مغل دربار کی اجازت اور سرپرستی کی محتاج تھی- اورنگزیب نے انگریزوں کو تجارت کی سہولتیں فراہم کیں، مگر جب بھی وہ قزاقی، دھوکہ یا تجاوز کے مرتکب ہوئے، سخت ردعمل بھی دیا-1668ء میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بمبئی کا علاقہ ہندوستانی سرکار سے لِیز پرلے لیا-
اورنگزیب کے ہی عہد میں، بنگال میں کمپنی نے پہلی جارحانہ پیش قدمی کی، جس کے جواب میں اورنگزیب نے انہیں عسکری طور پر شکست دی، جسے تاریخ میں بچوں کی جنگ ’’Child’s War‘‘کہا جاتا ہے- مغل سرکوبی کے بعد انگریزوں کو نہ صرف معافی مانگنی پڑی بلکہ دوبارہ تجارت کی اجازت بھی درخواست کے بعد ملی- عالمگیر کے پورے عہد میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو سیاسی یا فوجی رسوخ حاصل نہ ہو سکا اور اس کی حیثیت محض ایک محتاط تجارتی ادارے کی رہی- تاہم اس کے فوراً بعد کمپنی نے بمبئی، مدراس اور کلکتہ جیسے ساحلی مراکز میں قدم جمانے کی سنجیدہ کوششیں کیں اور یہی مراکز تھے جو بعد ازاں ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے قلعے ثابت ہوئے-
اورنگزیب کے بعد کمپنی کااثرورسوخ اتنا بڑھ گیا کہ بالآخر جب دلی میں محمد شاہ رنگیلا کا دورتھا، اُدھربنگال میں نواب سراج الدولہ کو انگریزوں نے دھوکے سے شکست دی اور بنگال چھین لیا- یہ پہلی بڑی واردات تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کر ڈالی-1757ء میں، پلاسی کے مقام پر انگریزوں اورنواب سراج الدولہ کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی- نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار میرجعفر نے غداری کی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں انگریزوں کی پہلی ریاست وجود میں آگئی-اس سب کے باوجود ہندوستانی مسلم قوم میں ابھی احساس کمتری پیدا نہیں ہوا تھا-خصوصاً مسلمان ابھی تک پدرم سلطان بُودکاشکارتھے-فرقہ پرستی میں غرق تھے -
جب انگریز نے بنگال لے لیا تواُنہیں دیوانی حقوق مل گئے-چنانچہ کلکتہ کی عدالت کے ایک جواں سال انگریزسیشن جج، جس کا نام ولیم جونز تھا، نے وہاں رائل ایشاٹک سوسائٹی کا آغاز کیا-یہ سوسائٹی ہندوستانیوں کے علوم و فنون کے مطالعہ کے لیے بنائی گئی تھی-ولیم جونز کی نگرانی میں یہاں سے مستشرقین کی ایک جماعت تیار ہوکر نکلی جس نے بعدازاں پورے ہندوستان کے مستقبل کو اپنے بیانیے کی مدد سے ساخت کیا-
یہاں ایک اہم نکتہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کی اُس ٹرانسفارمیشن کو سامنے لایاجاسکے جو ایک فعال خودی سے ایک غیرفعال خودی تک پیش آئی-ہم پچھلے ہزار سال کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مستشرقین کی واضح طورپر دوقسمیں- ایک وہ جو مسلمانوں کے عہدِ عروج میں مشرق آیا کرتے تھے اور دوسرے وہ جو مسلمانوں کے عہدِ زوال میں مشرق آیا کرتے تھے-وہ جو مسلمانوں کے دورعروج میں مشرق آیا کرتے تھے، ان میں گیارھویں صدی سے لے کر سولہویں صدی تک مشرق آنے والے مغربی سیّاح شامل ہیں-مثلاً یہ مارکوپولو سے واسکوڈے گاما تک چھ صدیوں پر محیط سیاحت ہے، جس کا تذکرہ تاریخِ یورپ میں ملتا ہے- جبکہ دوسرے عہد کے مستشرقین انگریزی استعمار کے عہد میں یہاں وارد ہوئے،جن میں سب سے بڑا نام سرولیم جونز کا ہے-ولیم جونز کی تیار کردہ جماعت نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی، جہاں ہندوستانی علوم کو بغرضِ افادہ جاری کیاگیا-
سیدسلمان ندوی کے بقول یہ دوطرح کے رویےتھے-پہلے رویے کو انہوں نے استفادے کا نام دیا اور دوسرے کو افادے کا-یعنی وہ مستشرقین جو مسلمانوں کے عہدِ ہائے حکومت میں مشرق کے اسفار کیا کرتے تھے، وہ استفادے کے لیے آتے تھے لیکن ولیم جونز کی جماعت کا مقصود افادہ تھا-استفادے اور افادے میں فرق یہ ہے کہ جب آپ استفادہ کرتے ہیں تو جس کسی سے آپ کو فائدہ ملناہے، اس کا رتبہ تسلیم کرتے ہوئے آپ اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں-آپ پہلے اسےخود سے بڑا اور عظیم مانتے ہیں، تب آپ اس کے علوم وفنون سے استفادہ کرتے ہیں-
جبکہ افادے میں آپ کسی اور احسان کا نہیں مانتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علوم حاصل کرکے آپ انہی پر احسان کر رہے ہیں- سلمان ندوی کے بقول وہ مستشرقین جو بغداد سے دلی کے زمانے تک مشرق کے مسلم ممالک میں آئےانہوں نے مشرقی علوم سے استفادہ کیا- جبکہ ولیم جونز کی جماعت نے،حاکمیت اور مفادپرستی کے جذبے سے ہندوستانی علوم وفنون پرقلم اُٹھایا-یہی وجہ ہے کہ اس نے ہندوستانی علوم و فنون کی توہین اور ہتک کی تاکہ ان کی ہندوستانی رعایا، اُن کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اپنے ماضی پر شرمسار ہو جائے اور خود کو نااہل تصورکرنے لگے-
مثلاً جنگِ پلاسی 1757 ء میں لڑی گئی اور انگریز وں کی پہلی ریاست وجود میں آئی- اس سے صرف 18 برس پہلے رچرڈ پارکرکالب و لہجہ استفادہ پسند مستشرق کا لب و لہجہ ہے-لیکن جنگِ پلاسی کے بعد جب ولیم جونز آتاہے، تو وہ ایک غالب اور فاتح، افادہ پسند مستشرق کے لہجے میں بات کرتا ہے- مثلاً جنگِ پلاسی سے اٹھارہ سال پہلےرچرڈ پارکر لکھتاہے،
’’اگر ہماری جہالت ہمیں ان سے محروم نہ رکھےتوہم مسلمانوں سے بڑے فوائد حاصل کرسکتے ہیں---مشرق نہ صرف مذہب بلکہ فطری علوم (سائنس) کا منبع ہے-مشرق کا میلان ان دونوں کی ترقی ہے‘‘-
جنگِ پلاسی سے صرف 25 برس بعد ولیم جونز لکھتا ہے کہ:
’’ہندوستانیوں کے تمام علوم لغوہیں‘‘-
وہ یورپ کو ایک شہزادی کہہ کر پکارتاہے اورایشیاکو اس کی کنیز-ولیم جونز کے الفاظ دیکھیے!
’’جس کسی نے ایشیا کا سفرکیاہے، خصوصاً وہ شخص جو ان ملکوں کے ادب سے واقف ہو، وہ فطری طورپر یورپی ذہانت کا ذکر کرکرے گا- مثلاً مشاہدہ جو اتنا ہی پراناہے، جتنا سکندرِ اعظم- اگرچہ ہم اس آرزو مند شہزادے (سکندر) کے استاد سے اتفاق نہیں کرسکتے جس نے کہا کہ ’ ایشیا کے لوگ پیدا ہی غلام ہونے کے لیے ہوئے ہیں‘- تاہم ایتھنز کا شاعر بالکل صحیح کہتاہے کہ ’یورپ خود مختار شہزادی ہے اور ایشیا گھریلو خادمہ ہے‘- لیکن اگر مالکن غیرمعمولی جلال والی ہو تو اس میں کیا شک ہے کہ نوکرانی کے پاس جمال ہوگا اور کچھ خصوصی مراعات بھی اس کو حاصل ہوں گی‘‘-
یعنی (ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کے الفاظ میں) ’’اگر مشرق، مغرب سے عشق باقی رکھتاہے تو یہ حسن باقی رہ سکتاہےورنہ نہیں‘‘-
یہاں ولیم جونز نے ایک تو ارسطو پر جھوٹا الزام باندھا ہے کیونکہ بعد میں محققین نے یہ ثابت کیا کہ ارسطو نے ایسی کوئی بات کہیں نہیں لکھی- دوسرا یہ کہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کے ماضی اور اپنے ماضی، دونوں کے بارے میں کذب بیانی سے کام لیا- کیونکہ اگر مسلمانوں کا ماضی شرمناک ہوتا تو ولیم جونز کے متقدمین یعنی اس سے پہلے آنے والے مستشرقین نے یہ اعتراف نہ کیا ہوتا کہ مسلمانوں کا ماضی شاندار تھا-ولیم جونز سے صرف 50 برس پہلے رچرڈ پارکر مسلم تہذیب کی عظمت کو تسلیم کررہاہے- اسی طرح ولیم جونز نے اپنے ماضی کے بارے میں بھی کذب بیانی سے کام لیا، کیونکہ رابرٹ بریفالٹ اورولیم ڈریپرنے یورپ کے تاریک ماضی کے بیان میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی-
ڈاکٹرغلام جیلانی برق،’’ یورپ پر اسلام کے احسانات‘‘ میں رابرٹ بریفالٹ اورولیم ڈریپر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ، یورپ سرتاسر جہالت میں غرق تھا- 1030ء تک دریائےساؤن کے کنارے انسانی گوشت بیچنے کی کتنی ہی دکانیں تھیں- برطانیہ میں کنٹربری کا لاٹ پادری جب درشن کے لیے چرچ کی بارہ دری میں نمودار ہوتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جویں چل رہی ہوتی تھیں- لندن میں لوگوں کو مکان بنانے کی تمیز نہیں تھی، اس لیے کئی مکان ایسے بنائے جاتے تھے کہ دوسرے گھروں کا راستہ روک لیتے- لوگ گھروں کے سامنے پاخانہ کرتے اورجس پانی سے کلیاں کرتے اسی سے ہاتھ منہ دھوتے تھے-
اسی طرح اگر ولیم جونز کے بقول، یورپ ایک شہزادی ہوتی تو ابن ِ خلدون اُن کے بارے میں کبھی یہ نہ لکھتا کہ:
’’یہ سب ایسے ہیں جو اپنی گردنوں میں غلامی کا پٹہ ڈال کر کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مال سمیٹنا چاہتے ہیں یا مقام کے بھوکے ہیں جیسے مشرق میں ترکی ممالک- اسی طرح جلالقہ کے گنواروں کااور ’فرنگیوں‘ (انگریزوں) کا حال ہے- کیونکہ اُن کی عادات میں حکومت کو اپنے خلوص کا ثبوت فراہم کرنا داخل ہے- اس لیے یہ غلامی سے نہیں شرماتے-کیونکہ اس طرح حکومت ان کو چُن لے گی اور انہیں عزت اور بلندی نصیب ہوگی‘‘-
یعنی ولیم جونز کی ساری بات ہی غلط بیانی ہےاوریہی اس عہد کے تمام مستشرقین کے قلم سے نکل رہا تھا- نوآبادیاتی عہد کے مشہور نقاد فرینٹز فینن(Frantz Fanon) کے مطابق کوئی بھی استعمار ایسا اس لیے کرتاہے تاکہ وہ اس خطے کے عوام میں احساس کمتری کا بیج بوکر بے یقینی کاپھل کاٹ سکے، جس پراس کا غاصبانہ قبضہ ہے-
چنانچہ ولیم جونز اور اس کی جماعت نے پورے شدومد کے ساتھ کتابیں، مضامین اورمقالے لکھے- ولیم جونز کےہی ایک، فکری خلف الرشید کا نام لارڈ میکالے ہے- لارڈ میکالے نے نوآبادیاتی عہد کے ہندوستان کا تعلیمی نظام تشکیل دیا-یہی (میٹرک، ایف اے والا) نظامِ تعلیم آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں رائج ہے-ایک موقع پر جب تجویز آئی کہ ہندوستانیوں کو اُن کے علوم اُنہی کے طریقے سے پڑھائے جائیں نہ کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظامِ تعلیم کے تحت-تو لارڈ میکالے نے جواب میں لکھا:
’’میں یہ کیسے تسلیم کرلوں کہ ایک ارفع ذہنی کارکردگی کی حامل قوم، ایک مقابلتاً جاہل قوم کو علم و ہنر سکھانا چاہتی ہے تو سکھانے کا طریقہ وہ اُس جاہل قوم سے سیکھے، جسے ابھی علم سکھاناہے‘‘-
انگریز استعمارکے رعونت آمیزرویے اور مسلمانوں کی مسلسل تذلیل کے عمل نے آخرکار ہندوستانی مسلمانوں کو مایوسی کے دلدل میں دھکیلنا شروع کر ہی دیا-وہ مسلم اشرافیہ جو کبھی ملوک التجار کہلاتی تھی، معذرت خواہانہ لجاجت کا شکار ہونے لگی-1857ء کی جنگِ آزادی میں مسلمانوں کی نمائشی سلطنت بھی ختم ہوگئی- دلّی تباہ کردی گئی - شہرفتح ہوتے ہی جنرل جان نکلسن، جنرل ولیسن اور میجر ولیم ہڈسن جیسے برطانوی افسران نے دہلی کے عام شہریوں پر اندھا دھند گولہ باری کروائی اور محض مسلمان ہونے کے شبہے میں ہزاروں افراد کو بغیر کسی مقدمے کے قتل کر دیا گیا- جو لوگ مغل شاہی خاندان سے منسلک تھے یا جن پر محض ہمدردی کا شبہ بھی تھا، چاہے وہ علما ہوں، شعرا، درباری، یا عام شہری،سب کو چُن چُن کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا- دہلی کے بیشتر مسلمان خاندانوں کے مکانات کو لوٹا گیا، پھر آگ لگا دی گئی- سینکڑوں خاندان بے دخل ہوئے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق شہر کی آبادی نصف سے بھی کم رہ گئی- جامع مسجد، لال قلعہ، اور دیگر تاریخی عمارات کو فوجی چھاؤنیاں یا گھوڑوں کے اصطبل بنا دیا گیا- علماء و صوفیاء بھی اس انتقام سے محفوظ نہ رہے- اخبارِ دہلی کے مدیر اور ممتاز عالم دین مولوی محمد باقر کو سرِ عام گولی مار کر شہید کیا گیا- دیگر علماء کو یا تو قید میں ڈال کر مار دیا گیا یا پھانسی دی گئی- ولی دکنی کے مزار کو بھی بے حرمتی سے فوجی اصطبل بنا دیا گیا- مساجد اور مدارس کی بے حرمتی کا یہ عالم تھا کہ ان میں قرآنِ مجید کی توہین تک کی گئی- خود مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرے سے میجر ہڈسن نے گرفتار کیا- ان کے بیٹوں، مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور پوتے کو مقبرے کے سامنے ننگا کر کے گولی مار دی گئی اور ان کی لاشیں لال قلعے کے دروازے پر لٹکا دی گئیں تاکہ دہلی کے لوگوں پر دہشت طاری ہو- بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کا مقدمہ چلا اور انہیں ’’غدار‘‘ قرار دے کر1858ء میں برما (موجودہ میانمار) کے شہر رنگون جلاوطن کر دیا گیا، جہاں وہ1862ء میں انتہائی مظلومیت اور تنہائی کے عالم میں 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئے- اُن کی بے بسی اور محرومی کا عکاس ان کا یہ مشہور شعر ہے:
|
کتنا ہے بدنصیب ظفرؔ دفن کے لیے |
1857 ء کے بعد مسلمانوں کے لب و لہجے میں وہ دم خم بالکل ہی مفقود ہو گیا جو اس سے قبل کبھی کبھار نظر آجاتا تھا اور جس کے سبب ہی جنگِ آزادی لڑی گئی تھی-دلّی کی تباہی کے بعد مسلمان اہلِ قلم بے حد محتاط ہوگئے-اپنے ماضی پر شرمندگی کاوہ احساس جو ولیم جونز اوراس کی بیانیہ ساز جماعت نے 100 برس سے آزمانا شروع کر رکھا تھا اور اس میں انہیں مسلسل ناکامی ہورہی تھی، یکایک پوری قوت سے مسلمانوں پر طاری ہوگیا-یہ اقبال کی پیدائش سے صرف 20 برس پہلے کی حالت ہے-1857ء کے بعد مسلمانوں کی معذرت خواہانہ اور عاجزانہ آوازوں میں سب سے بلند اور پُراثر آوازسرسید احمد خان کی تھی-اب سرسید احمد خان گویا ولیم جونز کے بیانیے کی تائید پر بہ اصرار کمربستہ تھے- اسی طرح سرسید احمد خان لارڈ میکالے کو ہندوستانیوں کے لیے گویا خدا کی نعمت سمجھتے تھے-میکالے کے بارے میں سرسید لکھتے ہیں:
’’اہلِ ہند کی بدنصیبی کا یہ دور 1835ء تک نہایت استحکام سے قائم رہا- آخر کار ایک نیک اورسچا مدبر یعنی لارڈ میکالے ہندوستان میں پیدا ہوا جو اس زمانے میں ہندوستان کی تعلیم کے بورڈ کا میرمجلس تھا اس نے دھوکا دینے والے طریقۂ تعلیم کو اعلانیہ ناپسند کیا‘‘-
الغرض! جب استعمار کاروں نے قصداً استعمار زدگان کے دلوں میں احساسِ کمتری کا زہر انڈیلنا شروع کیا تو صرف ایک صدی لگی اور مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے کہ ان کا ماضی بھی اُن کے حال کی طرح شرمناک ہے- کسی قوم کی روح کو تباہ کرنے کے لیے اس کے ماضی کوشرمناک ثابت کرنے سے بڑھ کر کوئی اسلحہ نہیں ہوسکتا-سرسید کی نیت جو بھی رہی ہو، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کا یہ خیال کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے ماضی کو بھول جائیں اورسرتاپا انگریز بن جائیں ورنہ فنا ہوجائیں گے، پوری طرح درست نہیں تھا-سرسید لکھتے ہیں:
’’اگرہم اپنی اصلی ترقی چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی مادری زبان تک بھول جائیں-تمام مشرقی علوم کو نسیامنسیاً کردیں-ہماری زبان یورپ کی اعلیٰ زبانوں میں سے انگلش یا فرینچ ہوجائے- یورپ ہی کے ترقی یافتہ علوم دن رات ہمارے دست مال ہوں-ہمارےدل و دماغ یورپین خیالات سے بجز مذہب کے لبریز ہوں‘‘-
الغرض! یہ تھا وہ پس منظر جس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمان اوّل اوّل بے یقینی کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوئے- ایک وقت تھا جب بغداد پر ہلاکو خان نے حملہ کرکے اہلِ بغداد کو غلام بنا لیا تھا- لیکن پھرکچھ ہی وقت میں قابض حکمران تاتاریوں نے محسوس کیا کہ مسلمان ان سے زیادہ تہذیب یافتہ ہیں- چنانچہ انہوں نے فاتح ہوکر بھی مسلمانوں کی تہذیب کو اپنانا پسند کیا- اقبال نےیہی بات ایک شعر میں کہی ہے:
|
ہے عیاں یورشِ تاتار کے افسانے سے |
لیکن ہندوستان میں اس کے برعکس ہوا-قابض قوم کی تہذیب ہم پر غالب آگئی-وجہ کیا تھی؟ اس میں شک نہیں کہ انگریز اس عہد میں علمی اورسائنسی اعتبار سے ہم سے بہت آگے تھے-لیکن کیا فقط یہی وجہ تھی اورہم ان کے علم اور ٹیکنالوجی کی چکا چوند سے متاثر ہوکر مغربی بیانیے کا شکار ہوئے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی مغلوب قوم اپنے آقاؤں کی تہذیب قبول نہیں کرتی- مثلاً بنی اسرائیل کئی مرتبہ مغلوب ہوئے، بخت نصر نے انہیں غلام بنایا، فرعون ِ مصرنے انہیں غلام بنایا ، لیکن وہ کبھی بھی کسی فاتح یا غالب سے مرعوب نہیں ہوئے-مصر میں بنی اسرائیل شہر کے سب سے نچلے درجے کے لوگ تھے- زیادہ ترسطبی تعمیرات کیلئے اینٹیں تھاپنے کا کام کرتے تھے-جبکہ مصرکی تہذیب اس وقت اپنے عروج پر تھی- مصر میں علوم و حکمت کے دریا بہتے تھے- حتیٰ کہ یونانی بھی مصریوں سے علوم سیکھ رہے تھے- ایسے عالم میں اتنی صدیوں تک غلام رہنے کے باوجود بنی اسرائیل نے کیوں نہ غالب قوم کی تہذیب اختیار کر لی؟ کیونکہ عہدِ غلامی میں بھی انہیں اپنے ماضی پر ہمیشہ فخر رہا- وہ غلام ہو کر بھی مرعوب نہ ہوئے اور خود کو برتر سمجھتے رہے -
لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی تہذیبی اقدار اور اپنے ماضی سے شرمانا سیکھ لیا تھا-یہاں تک کہ مسلمانوں کے وہ بزرگ جو ابھی تک اپنے ماضی کی عظمت بیان کررہے تھے، ان کے لہجے میں بھی احساسِ کمتری در آیا تھا-لیکن ان لہجوں میں جب اقبال کا لہجہ نمودارہوا تووہ تو بالکل مختلف تھا-
علامہ اقبال اور مسلم نشاۃِ ثانیہ کا خواب:
اقبال کے لہجے میں ایک داعیانہ شان تھی-اقبال نے جب علی گڑھ کالج کے طلبہ کے نام نظم لکھی توکہا:
|
اوروں کا ہے پیام اور، میرا پیام اور ہے |
طائرِ زیرِ دام سے مراد فرنگی تہذیب کے جال میں پھنس جانے والا غلام پرندہ ہے جبکہ طائرِ بام سے مراد ہے اسلام کی عظیم تہذیب کی دیوار پہ بیٹھا آزاد پرندہ - اقبال نےآغازِ جوانی سے ہی قوم کی ٹھیک ٹھیک نبض شناسی کرلی تھی- وہ جان گئے تھے کہ تمام تر مسئلہ احساسِ کمتری کا ہےاوریہی احساسِ کمتری قومی بے یقینی کا سبب ہے-چنانچہ اقبال نے 1904ء میں ’’قومی زندگی‘‘ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تو اس میں گویا قوم کے مرض کی پوری پوری تشخیص کردی-بنی اسرائیل کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ بنی اسرائیل کو کئی مرتبہ غلام بنایا گیا- ان سے ان کا وطن کئی بار چھینا گیا - لیکن بطورقوم وہ کبھی ختم نہیں ہوئے- اس کے برعکس وہ ہمیشہ سرفراز رہے اور دیگر اقوام ان کی مقروض رہیں- صاف ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو معاشی طورپر کمزورہونے سے بچائے رکھا اور صاف ظاہر ہے ایسا وہ اپنے احساسِ تفاخر کی وجہ سے کر پائے-اس کے بعد اقبال نے ہندوستانی مسلمانوں کا حال لکھتے ہوئے لکھا:
’’اپنے مکان کے اسبابِ آرائش ہی دیکھو تو معلوم ہو جائےگا کہ ذرا ذرا سی بات کے لیے ہم اقوامِ غیر کے محتاج ہیں اور روز بروز ہوتے جاتے ہیں- آپ کا لیمپ جرمنی میں بنا ہے- اس کی چمنی آسٹریلیا میں تیار ہوئی ہے-اس کا تیل روس سے آیاہے اور گندھک کی سَلائی جس سے یہ لیمپ روشن کیاجاتاہے سویڈن یا جاپان سے پہنچی ہے- کلاک جو آپ کی نشست گاہ کی دیوار پر آویزاں ہے، امریکہ کے کارخانوں میں تیارہوا تھا-اور وہ چھوٹی سی گھڑی جو آپ کی جیب میں ٹک ٹک کررہی ہے جنیوا کے کاریگروں کی صنعت کا نمونہ ہے‘‘-
یہ مضمون اقبال کی آنے والی تمام تر زندگی کا ''اُپنشد'' ہے - اسی مضمون میں پہلی بار اقبال نے مرض کا حل بھی تجویز کیا اور کہا کہ :
’’ان حالات کو مدنظررکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کو تعلیم کی تمام شاخوں سے زیادہ صنعت کی تعلیم پر زوردینا چاہیے- واقعات کی رُو سے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتاہوں کہ جو قوم تعلیم کی اس نہایت ضروری شاخ کی طرف توجہ نہ کرے گی وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوتی جائےگی- یہاں تک کہ صفحۂ ہستی پر اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہےگا- لیکن افسوس ہے کہ مسلمان بالخصوص اس سے غافل ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنی غفلت کا خمیازہ نہ اُٹھائیں‘‘-
اقبال کا انفراد یہ ہے کہ اس نے بنیادی طورپر اس طبقے کو اپنا مخاطب بنایا جو محنت کش تھا-اقبال نے ایسا اس لیے کیا کہ یہی زمانہ تھا جب احساسِ کمتری کے مارے ہوئے عامۃ الناس کو اشتراکیت کی جانب سے اُمید کی کرنیں نظر آرہی تھیں-انگریزی استعمار سے متنفرنچلا طبقہ جو نہ تو قابلِ انتخاب (Electable)کی فہرست میں آتاتھا اور نہ ہی اسے سرکاری نوکریاں میسر تھیں، تیزی کے ساتھ اشتراکی نعرے کا شکار ہورہاتھا-اقبال نے بھانپ لیا کہ اگرقوم کو اپنے پاؤں پر واپس کھڑاکرناہے تو اس کے اکابرین کو مخاطب کرنے کی بجائے اس کے عامۃ الناس کو براہِ راست مخاطب کیا جائے- کیونکہ اقبال کے نزدیک اگر قومی زندگی کی کچھ رمق ابھی باقی تھی تو وہ نچلے طبقے کے مسلمانوں میں باقی تھی- چنانچہ اقبال نے اپنے لکھاریوں کوبروقت بیدار کرنے کے لیےمسلسل لکھنا شروع کردیا-1917ء میں اقبال نے ’’رسالت مآب (ﷺ) کا ادبی تبصرہ‘‘ کے عنوان سے ایک مضمون اسی نیت سے لکھا، جس میں مسلمان شعراء اور ادیبوں کورسالت مآب (ﷺ) کے پسندیدہ شعروادب کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی-
اس مضمون میں اقبال نے رسالت مآب (ﷺ) کانظریۂ شعر بیان کیا-رسولِ اطہر (ﷺ) نے دو شاعروں پر تبصرہ فرمایا- اِمرأ القیس کے بارے میں فرمایا کہ ’’اشعر الشعرأ وقائدھم الی النار‘‘ یعنی وہ شاعروں کا تو سرتاج ہے لیکن شعراء کو اپنے ساتھ جہنم میں بھی لے کر جارہاہے-اقبال کے بقول رسالت مآب (ﷺ) نے ایسا اس لیے فرمایا کیونکہ ’’امراء القیس قوتِ ارادی کو جنبش میں لانے کی بجائے اپنے سامعین کے تخیل پرجادُو کے ڈورے ڈالتا ہےاور اُن میں بجائے ہوشیاری کےبے خودی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے‘‘-
اقبال نے مزید لکھاکہ:
’’ رسول اللہ (ﷺ) نے اپنی حکیمانہ تنقید میں فنونِ لطیفہ کے اس اہم اُصول کی توضیح فرمائی ہے کہ صنائع و بدائع کے محاسن اور انسانی زندگی کے محاسن، کچھ ضروری نہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہوں- یہ ممکن ہے کہ شاعر بہت اچھا شعر کہے لیکن وہی شعر، پڑھنے والے کو اعلیٰ علییّن کی سیر کرانے کی بجائے اسفل سافلین کا تماشا دکھا دے- شاعری در اصل ساحری ہے اور اس شاعر پر حیف ہے جو قومی زندگی کی مشکلات و امتحانات میں دلفریبی کی شان پیدا کرنے کی بجائے، فرسودگی وانحطاط کو صحت اور قوّت کی تصویر بناکردکھادے اور اِس طورپر اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف لے جائے- اس کا تو فرض ہے کہ قدرت کی لازوال دولتوں میں سے زندگی اور قوت کا جو حصہ اُسے دکھایا گیا ہے، اس میں اوروں کو بھی شریک کرے، نہ یہ کہ اُٹھائی گیرہ بن کر جو رہی سہی پونچی ان کے پاس ہےاُس کو بھی ہتھیا لے‘‘-
اس کے برعکس قبیلہ بنوعیس کے شاعرعنترہ کے بارے میں رسول اطہر (ﷺ)نے فرمایا کہ ’’اُسے دیکھنے کو میرا دل بے اختیار چاہتا ہے‘‘-اقبال نے رسالت مآب (ﷺ) کے، ایک بُت پرست عرب شاعر کے لیے ایسے والہانہ شوقِ ملاقات پر خوشگوارحیرت کا اظہارکرتے ہوئے لکھاہےکہ :
’’اللہ اکبر! توحید کا وہ فرزندِ اعظم (ﷺ) جن کے چہرۂ مبارک پر ایک نظرڈال لینا نظّارگیوں کیلئے دنیوی برکت اور اخروی نجات کی دوگونہ سرمایہ اندوزی کا ذریعہ تھا خود ایک بت پرست عرب سےملنے کا شوق ظاہر کرتاہے کہ اس عرب نے اپنے شعر میں ایسی کون سی بات کہی تھی‘‘-
پھر اقبال نے خود وضاحت کرتے ہوئے لکھاکہ:
’’ حضورخواجۂ دوجہاں (ﷺ) نے جو اس قدر شعر کی تعریف فرمائی اس سے صنعت کے ایک دوسرے بڑے اصول کی شرح ہوتی ہے کہ صنعت حیاتِ انسانی کے تابع ہے اس پر فوقیت نہیں رکھتی‘‘-
در اصل عنترہ کی شاعری میں زندگی کی مشکلات کاایک شانِ دلفریبی کے ساتھ ذکرتھا نہ کہ مایوسی اورکربِ وجود کے اظہارکے ساتھ-پھر اپنے مضمون کے آخر میں اقبال لکھتے ہیں:
’’تمام وہ باتیں جن کی وجہ سےہم جاگتے جاگتے اونگھنے لگیں اور جو جیتی جاگتی حقیقتیں ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں (کہ انہی پر غلبہ پانے کا نام زندگی ہے)، اُن کی طرف سے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، انحطاط اور موت کا پیغام ہے- صنعت گر کو چُنیا بیگم کے حلقۂ عشاق میں داخل نہ ہونا چاہیے-مصورِ فطرت کو اپنی رنگ آرائیوں کا اعجاز دکھانے کے لیے افیون کی چسکی سے احتراز واجب ہے- یہ پیش پا افتادہ فقرہ جس سے ہمارے کانوں کی آئے دن تواضع کی جاتی ہے کہ کمال ِ صنعت اپنی غایت آپ ہے- انفرادی، اجتماعی انحطاط کا ایک عیّارانہ حیلہ ہے جو اس لیے تراشا گیا ہے کہ ہم سے زندگی اور قوت، دھوکا دے کر چھین لی جائے- غرض یہ کہ رسول اللہ (ﷺ) کےوجدانِ حقیقی نےعنترہ کے شعر کی خوبیوں کا جو اعتراف کیا، اس نے اصل الاصول کی بنیاد ڈال دی کہ صنعت کے ہرکمال کی صحیح ارتقأ کیا ہونی چاہیے‘‘-
الغرض! اقبال نے ہرطریقہ اختیارکیا اوردوسروں کو بھی ہرطریقہ اختیارکرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں کیں کہ نوجوان ہندوستانی مسلم کچھ تدبر کرے اور یہ سوچے کہ وہ کس ’’ گَردوں کا ٹوٹا ہوا ستارہ ‘‘ تھا اورپھر جب اسرارِ خودی کی اشاعت ہوئی توصرف ہندوستان میں ہی نہیں انگلستان میں بھی اقبال کے اس نئے اور منفرد لب و لہجے کی گونج پہنچی جس میں نہایت دو ٹوک الفاظ میں یہ بتایا گیا تھا کہ مفاہمت، قبولیت، تابعداری، معافی، نرمی اور کائنات سے دوستی کی باتیں کرنے والے تمام نظریات بنیادی طورپر نخچیر(prey) کی اخلاقیات ہے-مجبوروں کی یہ اخلاقیات اس تفاوت کی وجہ سے ہے، جو ہر نخچیر نے جان رکھاہے کہ ہر شکاری (predator) اس کا دشمن ہے-نخچیرکاتناظر بائنری ہے-اسے ہرجھاڑی کے پیچھے اپنا دشمن دکھائی دیتاہے-اس کے لیے یہ دنیا بلیک اینڈوائٹ ہے-وہ اپنے بچوں کو محفوظ رہنے کا درس دیتاہے-اسے شکاریوں کے ظلم سے بچنے کے طریقے سکھاتاہے-اس کے برعکس صیاد (predator) کی اخلاقیات بالکل مختلف ہے-اس کا شکار اس کا دشمن نہیں بلکہ وہ اس کی حفاظت میں ہے-وہ مملوک نہیں خود مالک ہے- اسے دنیا بائنری میں نظر نہیں آتی، کیونکہ جھاڑیوں کے پیچھے اس کا کوئی دشمن نہیں چھپا ہوا- وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں سوچ سکتا-وہ اپنے بچوں کو سکھاتاہے کہ باہر کی دنیا ان کا گھر ہے- وہ آزاد ہیں، جہاں چاہیں گھومیں، جو چاہیں کھائیں، لیکن اسراف حرام ہے ’’کلوا واشربواولاتسرفوا‘‘-وہ اپنے بچوں کو باقی شکاریوں کے ظلم سے بچنے کے طریقے نہیں سکھاتا، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ تم نے خود ظلم نہیں کرنا- تمہارے ہاتھ اور زبان سے تمام سلامتی پسند محفوظ رہیں-نخچیرمملوک ہے، لیکن صیاد مالک ہے-مثلاً شاہین اپنے آپ کو آسمان کا مالک سمجھتا ہے لیکن وہ خود پر ضرورت سے زیادہ شکار کو حرام سمجھتاہے-
یہ تاثر تھا جو ’’خودی کے راز‘‘ کے طورپر اقبال نے اسرارِ خودی (Secrets of Self) میں پیش کیا اورصرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ہراُس تصوف کو آڑے ہاتھوں لیا جو خودی کی نفی کا سبق دیتا تھا- اور اس کے ساتھ اس ملائیت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جو ملوکیّت سے مراعات و مناصب لینے کیلئے عوام کا استحصال کرتی ہے -
پہلی جنگِ عظیم کے بعد اقبال بھانپ گئے تھے کہ برطانیہ اب دیر تک دنیا کی سپرپاورنہیں رہےگا-وہ یہ بھی بھانپ گئے تھے کہ برطانیہ کی کالونیوں میں اب بڑے پیمانے پر سیاسی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں-پیامِ مشرق کے دیباچے میں اقبال نے برطانیہ ہی نہیں پورے یورپ کے، مستقبل میں عجمیت کاشکارہوجانےکی پیشگوئی کی تھی، جواب حرف بحرف درست معلوم ہوتی ہے-اسی سیاسی بصیرت کی روشنی میں اقبال نے جان لیاتھا کہ جلد ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے قومی شناخت کا مسئلہ پیش آنے والا ہے-
اس پر مستزاد کانگرس سے منسلک مسلمان علمأ خصوصاً مولانا ابولکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی اپنے مؤقف کا اظہارکرچکے تھے جو مشترکہ ہندوستانی قومیت کا مؤقف تھا-اقبال اپنے نظریۂ خودی کی وجہ سے ایسے شنکری وجودیت (متحدہ قومیت) کو کیونکر قبول کرسکتے تھے چنانچہ انہوں نے عمر کے آخری چند برس گویا مسلم قومی شناخت کی جنگ لڑتے ہوئے گزارے- کانگریسی ملاؤں کانظریہ یہ تھا کہ قومیت مذہب سے نہیں ہوتی، بلکہ وطن سے ہوتی ہے، بالفاظ ِ دیگر وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہماری قومیت ہندوستانی ہے نہ کہ مسلمان- شنکر اچاریہ کی وجودیت کے تحت ایک مولانا نے دلّی کے ایک اجتماع میں جب اسی نظریہ کا اعادہ کیا اور کہا کہ:
’’فی زمانہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں‘‘-
علامہ اقبال اس قدر ناراض ہوئے کہ انہوں نے مندرجہ ذیل اشعارکہے:
|
عجم ہنوز نداند رموزِ دیں، ورنہ |
ان اشعار کا اردومیں مفہوم کچھ یوں ہے کہ، عجم(یعنی اہلِ ہند) کو ابھی تک دین کے رموز کا علم نہیں ہے کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی جو دیوبند کے عالم ہیں، انہوں نے منبر پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ ’’ملتیں وطن سے بنتی ہیں‘‘، یہ تو مقامِ محمد عربی (ﷺ) سے بے خبری کا ثبوت ہے- دین وہی ہے جو آپ کو محمد مصطفےٰ (ﷺ) تک پہنچائے- اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو پھر باقی سب ابولہب کا راستہ ہے، دِین کا نہیں-
ان اشعار کی شہرت ہوئی تو طالوت نامی ایک شخص نے مولانا حسین احمدمدنی علیہ الرحمہ سے ایک خط کے ذریعے وضاحت مانگی- مولانا مدنی نے جو جواب دیا، وہی جواب طالوت نے علامہ اقبال کو بھیجا اور یوں ایک بحث شروع ہوئی جسے تاریخ میں ’’معرکۂ دین وطن‘‘ کے نام سے جانا جاتاہے-ان خطوط میں مولانا مدنی نے جو مؤقف اختیار کیا وہ درج ذیل تھا:
قرانِ کریم میں قوم، ملت اور اُمت، تین اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں- قران کے مطابق ’’قوم‘‘ ایک علاقائی تصور ہے اور اس کا تعلق کسی خطۂ زمین، کلچر اور علاقے کے ساتھ ہے- مولانا نے قرانی آیات سے مثالیں پیش کرتے ہوئے لکھا کہ قومِ لوطؑ، قومِ ابراہیمؑ، قومِ نوحؑ، قوم ھودؑاورقوم صالِحؑ کی اصطلاحات قران میں علاقائی اقوام کے لیے الگ الگ استعمال ہوئی ہیں-ان انبیا کی اقوام علاقائی تھیں، نہ کہ عالمگیر- اس کے بعد مولانا مدنی نے لفظ’’ملّت‘‘ کی مثالیں دیں اور کہا قرآن کے مطابق ملّت مذہب سے ہوتی ہے، جیسا کہ قران میں ملّتَ ابراہیم َ حنیفا کی اصطلاح استعمال ہوئی یا حدیث میں ’’الکفر ملت واحدہ‘‘ یعنی کفر ایک ملت ہے کے الفاظ آئے ہیں، سو اس لیے ملت تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم بنا رہے ہیں، لیکن بطورقوم ہم ہندوستانی ہی ہیں- مولانا نے لکھا کہ اُمت پوری انسانیت کو کہتے ہیں ، جیسا کہ قرآن میں آیا: ’’ کان الناس الّااُمۃً واحدہ‘‘ یعنی تمام انسان ایک اُمت ہیں-
اقبال نے ان وضاحتوں کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ’’الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا‘‘- اقبال نے کہا ہندوستانی مسلمان صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے الگ قوم ہیں اور ہر لحاظ سے یہ ہندوؤں سے مختلف ہیں- ان کی زبان، ثقافت، لباس، رہن سہن، تہذیب و تمدن ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ہندوؤں سے جُدا ہے- اگر قوم، زبان، کلچر اور رسم و روایات سے بنتی ہے تو پھر ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمان ہندوؤں سے اس قدر مختلف کیوں ہیں؟ اس ’’کیوں‘‘ کا جواب نہایت واضح ہے کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے ہندوؤں سے الگ ہیں-
معرکۂ دین و وطن ایک علمی مباحثہ تھا جو اقبال کی وفات تک جاری رہا اور دونوں طرف کے لوگ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی بالآخر خاموش ہوگئے-دراصل اقبال کی کوشش تھی کہ ہندوستانی مسلمان قومیت اور نیشن سٹیٹ کے اس تازہ غلغلے کی زد میں آکر، کہ جو پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا اور عیسائیت کا خاتمہ کر چکا تھا، کہیں اپنے عظیم تہذیبی سرمائے کو کھو نہ دیں- اقبال یورپ میں نیشن سٹیٹ کے جن کو بوتل سے نکلتا ہوا دیکھ چکے تھے- اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ قومیت کا یہ نظریہ جس کی بنا وطن پر ہے، کس حد تک خطرناک ہوسکتاہے- انہوں نے اسی نظریے کی بنا پر اہلِ یورپ کے لیے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ:
|
دیارِ مغرب کے رہنے والو! خدا کی بستی دکاں نہیں ہے |
پھر اقبال کی پیش گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی- اقبال نے یہ پیش گوئی 1907ء میں کی تھی، جس کے ٹھیک 7 سال بعد یورپ میں پہلی جنگِ عظیم ہوئی، جس کے نتیجے میں ڈیڑھ کروڑ انسان مارے گئے- پھر یہ جنگ بند ہوئی بھی تو عارضی طورپر- 1940ء میں یہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی اور اس بار اس نے 6کروڑ انسانوں کی جان لی اور 60فیصد یورپ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا- اتنی بڑی تعداد میں انسان، زمین کی تاریخ میں کبھی، قتل نہ کیے گئے تھے-
اقبال کا یہ مؤقف تھا کہ چونکہ اہلِ یورپ نے عیسائی مذہب کے جھنڈے کو خیر باد کہہ دیا ہے اور وطنی قومیت کے اپنے الگ الگ جھنڈے اٹھالیے ہیں اس لیے اب ممکن نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری کے ساتھ رہ سکیں-اقبال کا کہنا تھا کہ:
|
اِن تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے |
اقبال کا نظریہ بہت ہی واضح اور دو ٹوک تھا:
|
قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں |
پھر جب پہلی جنگِ عظیم کے بعد یورپ کو احسا س ہوا کہ عیسائیت کا مشترکہ پرچم پھینک دینے اور وطنی قومیت کا پرچم اٹھالینے کےبعدان میں کس قدر رنجش، جھگڑا اورلڑائی بڑھ گئی ہے، تو یورپ نے دوبارہ متحد ہوجانے کی کوششیں شروع کردیں اور پھر وہ دوبارہ جمع ہوئے اور اس بار عیسائیت کا جھنڈا تو نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اتحاد کو ہی ترجیح دی- لیگ آف نیشنز جوبعد میں اقوامِ متحدہ کہلائی، وجود میں آئی-اقبال ابھی زندہ تھے جب لیگ آف نیشنز کے متحدہ پرچم تلے یورپ کے لوگ اکھٹا ہونا شروع ہوئے- تب اقبال نے کہاتھا:
|
تفریقِ ملل حکمتِ افرنگ کا مقصود |
فلسفۂ پاکستان:
تصریحاتِ بالا سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا تصور کسی استبداد کا ردعمل نہیں تھا، بلکہ یہ تصور صدیوں میں تشکیل پاتی ہوئی ایک قوم کی شناخت اور اُس کی فطری ضروریات کا قدرتی تقاضا تھا-بالفاظِ دیگر پاکستان تاریخ کے تسلسل کی ایک ایسی وجودی حقیقت تھی جسے فقط اپنے وقت پر مشہود ہونا تھا، نہ کہ بننا تھا-
ہندوستانی مسلمان تاریخی اعتبار سےایک ایسی قوم تھے جن کی روحانی ساخت میں وجود وشہود اورتصوریت و تجربیت جمع ہوگئے تھے-وہ صوفی ہوکربھی ترکِ دنیا کے قائل نہ تھے- وہ کارو باری تھے، لیکن سُودخورنہیں تھے-وہ فعال، مہذب و متمدن اورپڑھے لکھے تھے-وہ ہندوستانی تھے لیکن ان کی روحیں عرب کے ریگزاروں میں محو طواف رہتی تھیں-اقبال کے الفاظ میں:
|
عجمی خُم ہے تو کیا مَے تو حجازی ہے مری |
اقبال کو بہت اچھی طرح سے احساس تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان اگر ہندوؤں کے ساتھ رہے تو اُن کا بچا کھچا ’’دَم خم‘‘ بھی جلدفنا ہو جائے گا-کانگرسی علماء کے ساتھ بحث میں انہوں نے کئی بار واضح کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں فرق صرف ظاہری مذہب کا ہوتا تو اوربات تھی، یہ فرق دو الگ الگ فطرتوں(natures) کا فرق ہے-مسلمان کے خمیر میں خودی کے استکمال کا جذبہ گندھا ہوا ہے-اقبال کا خیال تھا کہ اگرہندوستانی مسلمانوں کو کھل کر اسلامی تعلیمات کے تحت جینے کا موقع ملا تو یہ اپنی خلّاقی سے دنیا کو حیران کر دیں گے-
اقبال کا مؤقف تھا کہ:
|
قہاری و غفاری و قدوسیِ و جبروت |
اقبال کویہ بھی اُمید تھی کہ اگر ہندوستانی مسلمانوں کو الگ وطن میسر آجائےتووہ شریعتِ اسلامی کی روشنی میں دنیا کو بہترین اقتصادی نظام کا نمونہ دکھاسکتے ہیں- اقبال اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اسلامی شریعت کو اگر آزاد مسلم ریاست کے ماحول میں علم و بصیرت کے ساتھ نافذ کیا جائے، تو ہر انسان کا کم از کم حقِ معاش اور بنیادی اقتصادی تحفظ، یقینی بنایا جا سکتا ہے- ان کا یہ عقیدہ وقت کے ساتھ پختہ ہوتا چلا گیا کہ ہندوستان میں امن و استحکام اور مسلمانوں کی معاشی فلاح، محض ایک ایسی ریاست سے ممکن ہے جو ان کے دینی و تہذیبی شعور کی ترقی کی ضمانت بنے - ایسی ریاست جو صرف مذہبی علامت نہ ہو بلکہ ایک ’’روحانی جمہوریت‘‘ کی شکل اختیار کرے- اپنے ایک خط میں اقبال نے قائدِ اعظم کو لکھا:
’’اسلامی قانون کے طویل و عمیق مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ اگر اس نظام قانون کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کیا جائے تو ہر شخص کے لیے کم از کم حقِّ معاش محفوظ ہو جاتا ہے لیکن شریعت اسلام کا نفاذ اور ارتقاء ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستوں کے بغیر اس ملک میں ناممکن ہے- سالہا سال سے یہی میرا عقیدہ رہا ہے اور اب بھی میرا ایمان ہے کہ مسلمانوں کی غربت (روٹی کا مسئلہ ) اور ہندوستان میں امن و امان کا قیام اسی سے حل ہوسکتا ہے‘‘-
خود قائدِ اعظم نے بھی جب اقبال کے خطوط شائع کروائے تو ان کے دیباچے میں لکھا کہ:
’’میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطوط عظیم تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، خصوصاً وہ جومسلم انڈیا کے سیاسی مستقبل کے بارے میں ان کے نظریات کو واضح اور غیر مبہم طور پر بیان کرتے ہیں- ان کے نظریات بہت حد تک میرے اپنے نظریات سے ہم آہنگ تھے لہٰذا انڈیا جن مسائل سے گزر رہا تھا ان کا احتیاط سے جائزہ لینے اور ان کے مطالعے کے بعد آخر کار انہوں نے مجھے انہی نتائج تک پہنچنے میں راہنمائی کی اور وہی چلتے چلتے مسلم انڈیا کی متحدہ خواہش کی صورت میں 23 مارچ 1940ء کی آل انڈیا مسلم لیگ کی قرار داد لاہور میں ظاہر ہوئے جسے مقبول طور پر ’’قرار داد پاکستان‘‘ کہا جاتا ہے- (ایم-اے-جناح)‘‘-
اقبال کے خط کے اقتباس میں ’’شریعتِ اسلام کے نفاذ اور ارتقاء‘‘ کے الفاظ سے اس غلطی فہمی کا احتمال ہے کہ اقبال بھی شاید اپنی مجوزہ آزاد ریاست کو ایک مذہبی ریاست ہی بنانا چاہتے تھے- اصل انگریزی متن میں ’’ڈیولپمنٹ اِن شریعہ‘‘ کے الفاظ ہیں، جو نہایت اہم ہیں اور اسی ڈیولپمنٹ اِن شریعہ کی تفصیل پر اقبال کی ایک پوری تصنیف، ’’دی ری کنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ اِن اسلام‘‘ موجود ہے- اقبال کے نزدیک شریعت جامد قانونی ضابطہ نہیں، بلکہ ایک ارتقائی شعور ہے جو انسانی آزادی، اجتہادی قوت اور روحانی جمہوریت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر آگے بڑھتا ہے- ان کے تصورِ ریاست کا مرکز قانون کا اطلاق نہیں بلکہ انسان کی داخلی خودی کی تعمیر ہے جو اجتماعی سطح پر، ایک بامعنی تہذیبی وحدت کی صورت اختیار کرتی ہے- گویا اقبال ایک ایسے وطن کے خواہش مند تھے جہاں شریعتِ اسلامی کی ڈولپمنٹ(اجتہاد) ممکن ہوسکے-
پھرقراردادِ پاکستان میں مزید واضح ہوگیا کہ پاکستان بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا-قرادادِ پاکستان کی شکل میں در اصل ہندوستانی مسلمانوں سے ان کی تہذیبی شناخت پر تائید اور گواہی مانگی گئی تھی- آیا وہ خود کو ایک مستقل تہذیبی اکائی سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا طرزِ زندگی، ان کے دینی تصورات اور سماجی اقدار، باقی ہندوستانی اقوام سے مختلف ہیں؟ اگر ہاں، تو پھر ہندوستان کے جمہوری ڈھانچے میں اکثریتی غلبے کے باعث، ان کے تہذیبی و قانونی امتیاز کیلئے الگ ریاست ناگزیر ہے- اسی سوال کو ایک اجتماعی رائے میں ڈھالا گیااور لاکھوں مسلمانوں نے اس تصور کی تائید کر کے اس کے حق میں اپنی آواز شامل کی-
اقبال 1938ء میں وفات پا گئے- پاکستان 1947ءکو وجود میں آیا-دوسری جنگ عظیم ختم ہوچکی تھی- چائنہ بھی جاپان کے تسلط سے آزاد ہوچکاتھا- ایٹم بم آزما لیاگیا تھا اور دنیا یورپی نیشنلزم کے خوفناک نتائج بھگت رہی تھی-یہ وہ وقت تھا جب دنیائے فلسفہ میں شناخت کے مسئلے پرطوفانی قسم کے مباحث جاری تھی- پوسٹ ماڈرنزم نمودار ہورہاتھا- پوسٹ ماڈرنزم، جو بظاہریورپی نیشنلزم کے خلاف ایک فلسفیانہ احتجاج تھا آزادیِ فکر اورشناخت شکنی کی تحریک بن کر ظاہر ہوا- پوسٹ ماڈرنزم کا نعرہ تھا، اقوامِ عالم کو ان کے مراکز سے الگ کردو! پوسٹ ماڈرنزم ہرمہابیانیے کا ناقد تھا-قرآن، بائبل، داس کیپٹال، سب کا-
چنانچہ یورپ لامرکزیت کے فکری طوفان کی سب سے بڑا تجربہ گاہ بن گیا- شناختوں، خاندانوں اور تہذیبی مراکز سے لاتعلقی نے وہاں کے انسان کو اپنی جڑوں سے کاٹ دیا ہے- خاندانی نظام، جو کسی بھی قبیلے، قوم یا تمدن کی اکائی ہوتا ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے- اب ثقافت صرف نمائشی تقریبات، عجائب گھروں یا تہواروں میں بچی ہے، اصل زندگی میں انسان محض انفرادی حیوان بن چکا ہے، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف اتنا رہ گیا ہے: ’’کماؤ، کھاؤ، پیو ، عیاشی کرو اورسوجاؤ‘‘-
اقبال نے پیامِ مشرق کے دیباچے میں یہ پیشگوئی بہت پہلے کردی تھی کہ یورپ جس راہ پر روانہ ہے بالآخر عجمیت کا شکار ہوجائےگا- اقبال کے الفاظ:
’’خالص ادبی اعتبار سے دیکھیں تو جنگِ عظیم کی کوفت کے بعد یورپ کے قوائے حیات کا اضمحلال ایک صحیح اور پختہ ادبی نصب العین کی نشوونماکے لیے نامساعد ہے-بلکہ اندیشہ ہے کہ ان اقوام کی طبائع پر وہ فرسودہ سست رگ اور زندگی کی دشواریوں سے گریز کرنے والی عجمیت غالب نہ آجائے جو جذباتِ قلب کو افکارِ دماغ سے متمیز نہیں کرسکتی-البتہ امریکہ مغربی تہذیب کے عناصر میں ایک صحیح عنصر معلوم ہوتاہے اور اس کی وجہ شاید یہ کہ یہ ملک قدیم روایات کی زنجیروں سے آزاد ہے اور اس کا اجتماعی وجدان نئے اثرات و افکار کو آسانی سے قبول کر سکتا ہے‘‘-
چنانچہ اقبال کو اس شناخت شکن عہد میں قوم کی بقا کے سوال کا جواب اسلام کے نظریۂ قومیت میں ملا اور اقبال نے پورے جوش کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ اسلامی تہذیبی شناخت اب بھی وہ واحد رشتہ ہے جو مسلمانانِ عالم اور بالخصوص مسلمانانِ ہند کو فنا ہونے سے بچا سکتا ہے- یہی شناخت عربوں، فارسیوں اور روسی ریاستوں کی شناخت ہے اور یہی شناخت، اگر فکری طور پر زندہ رکھی جائے، تو مسلمانوں کی روحانی مرکزیت کو عالمی بیگانگی سے بچا سکتی ہے اور آج بھی یہی مرکزیت، پوسٹ ماڈرن زوال کے مقابل وہ زندگی بخش قوت ہے جس سے فلسفۂ پاکستان پھر سے نئی معنویت کے ساتھ ابھر سکتا ہے-
٭٭٭
کتابیات:
v The Reconstruction of Religious Thought in Islam by Allama Muhammad Iqbal
v An Essay on the Usefulness of Oriental Literature by Richard Parker
v مقدمہ ابن خلدون
v اسرارِ خودی :علامہ محمد اقبال
v ڈاکٹروزیرآغاکا خطبہ صدارت: ڈاکٹرناصرعباس نیّر
v History of Muslim Philosophy by M.M. Sharif
v ثقافت: خلیفہ عبدالحکیم
[1]’’آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کردیااور تم پر اپنی نعمت پوری کردی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا‘‘-(المائدہ:3)
[2](قریش:2)